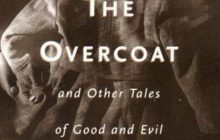عزت بلوچ
لاپتہ شبیر بلوچ ’’ جسے ہم لکّی کہتے ہیں‘‘ نے ایک بار کہا تھا کہ میں اپنے ہی حق کے لئے کیوں مروں، حق بھی میرا اور زندگی بھی میری۔ میرا حق ہے، بغیر کسی مسئلے کے مجھے مل جائے۔لکّی کی یہ بات سادہ تھی، لیکن سادہ باتوں کو کوئی کیونکر سمجھنے کی کوشش کرے،خصوصاً وہ لوگ ایسی باتوں کو سمجھنے کے لئے کیوں خود کو پریشاں کریں کہ جنہیں لوگوں کو لاپتہ کرنے اور مارنے کا اختیار اُنکی بے مہاراختیار اور ہماری بے اختیاری نے دے دیا ہے۔
کسی نے کہا ہے کہ اپنے حق کے لئے جان کی قربانی عبادت ہے، اس بات سے مفر نہیں کہ جان کی قربانی اپنے حق کے لئے عظیم ترین عمل ہے۔ لیکن اس عمل کو کر گزرنے کے لئے اپنے ایک بنیادی حق یعنی زندگی سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، زندگی سے دستبرداری بذات خود ایک خوبصورت عمل نہیں ہے۔انسان سے اسکی زندگی چھیننے اور انسانی عزتِ نفس کو مجروح کرنے جیسا بدصورت عمل شاید ہی دنیا میں ممکن ہو۔
بلوچستان کی مٹی بھی عجیب ہے، نسلوں سے زیر عتاب ہے لیکن انصاف و برابری کی جدوجہد کرنے والے سپوت پیدا کرنے کا سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے۔ بلوچستان میں ایک طبقہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے جس نے ظلم کے ضابطوں کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ اسکولوں میں ’’تعلیم‘‘ کے نام پر نوجوانوں کو بے علم کرکے گمراہ کرنے کی طوفانِ بد تمیزی کے باوجود بھی بلوچستان کے ایک بہت بڑے طبقے نے اس سے خود کو محفوظ کررکھا ہے۔
میڈیا کی بے دلیل چیخ و پکار بھی ان اذہان کو منفی حوالے سے متاثر کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ذاتی زندگی میں مگن رہنے کو کامیابی کا نام دینے کی’’ این جی اوئی‘‘ سوچ بھی بلوچستان کی انقلابی تخم کو ابھرنے سے نہ روک سکی ہے۔ پاکستانی اداروں میں رائج سرکاری تعلیم کی بابت کسی دوست نے خوب کہا ہے کہ ’’اگر کوئی دس سال مسلسل سرکاری اسکولوں میں سرکاری نصاب پڑھے، دوسرے کتابوں کی جانب توجہ نہ دے تو اس کے انکار کرنے کی صلاحیتیں ناکارہ ہوجاتی ہیں۔
بلوچستان سے لاپتہ ہونے والے بھی ایسے ہی لوگ ہیں جو ریاستی بیانیے کے برعکس سوچتے ہیں۔کسی لاپتہ شخص کا دوست ہونا کیسا بھیانک تجربہ ہے، یہ مجھ سمیت بلوچستان کے بیشتر نوجوان جانتے ہیں۔ کسی گمشدہ شخص کی بیٹی ہونا کتنا اذیت ناک تجربہ ہے، سمی، ھانی، مہلب سمیت بلوچستان کی ہزاروں بچیاں اس تلخ تجربے کی زندہ مثالیں ہیں۔
کسی لاپتہ شخص کی، یا تشدد سے مرنے والے اور مسخ شدہ لاش کی شکل میں برآمد ہونے والے نوجوان کی ماں، باپ، بہن بھائی کے درد کا احساس الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اب تک ایسا کوئی لفظ ایجاد نہیں ہوا ہے جو انسانی جذبات کو ویسے ہی بیان کرے جیسا کہ وہ محسوس کررہا ہے۔شاید اسی لئے کہتے ہیں کہ آنکھوں کی زبان الفاظ سے کہیں زیادہ پر اثر ہوتی ہے۔ بد قسمتی سے، بلوچستان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، باپ اور بدقسمت دوست ان تجربات سے باربار گزر رہی ہیں، لیکن ابھی تک اغواء کا اختیار رکھنے والے اختیار داروں نے اس پالیسی کو روکنے کے بجائے جاری رکھا ہے۔
یہ بات کسی اور کے لئے حیرانی کی بات ہو تو ہو، لیکن میرے لئے حیرانی کی بات نہیں کہ بلوچستان کا ایک مخصوص مگر وسیع طبقہ ہی کیوں لاپتہ ہونے کی، یا مسخ شدگی کی پالیسیوں کا شکار ہے۔یہ طبقہ زندگی سے بھرپور طبقہ ہے۔ کتابوں اور نئے خیالات کا متلاشی طبقہ، لوگوں سے جنوں کی حد تک محبت اور عام لوگوں پر غیر متزلزل اعتماد کرنے والا طبقہ۔ اس قبیل کے لوگوں کی وجہ سے ہی ہم را و موساد کے ایجنٹ، بھٹکے ہوئے، مٹی بھر اور نہ جانے کیسے کیسے ’’قابلِ فخر‘‘ اعزازات حاصل کرچکے ہیں۔
یہ وہ طبقہ ہے جسے ہر شخص کی پسماندگی، ناخواندگی، تنگدستی انتہا کی حد تک ستاتی ہے۔ سربازار جب کوئی بزرگ یا نوجوان کسی ’’انسان نُما‘‘ مسلح شخص کی جانب سے تلاشی کی ذلت آمیز عمل سے گزرے تو انہیں تکلیف سونے نہیں دیتی۔ اسکول کے بجائے جب یہ لوگ کسی بچے کو چائے والے کے پاس دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہوجاتی ہیں، یہ الگ بات کہ بچہ اسکول سے زیادہ روز مرہ کی تجربات سے زیادہ سیکھ سکتاہے۔ لیکن اسکول جانے کی سکت نہ ہونا پسماندگی کی علامت ہے اور یہ لوگ ہر اُس علامت کو مٹانے کے لئے کوشاں ہیں جو انسان کی بے توقیری کرے۔
انسانی عظمت کی بلندی و آزادی کے لئے جدوجہد کرنے وا لے ان لوگوں کے لئے اب تک جو لفظ سب سے زیادہ مستعمل ہوئی ہے، وہ غداری کا ہے۔مقتدرہ طاقتیں اپنی میڈیا، اپنے تعلیم اور اپنی منبر کے ذریعے اپنے بنائے ہوئے اصطلاحوں کو زبان زد عام کرنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔لیکن یہ لوگ جنہیں غداری کی چھاپ لگی ہوئی ہوتی ہے اس بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے کہ معاشرہ بے حس ہو سکتا ہے۔ ان کے خیال میں ایک مربوط سسٹم لوگوں کی ذہنوں کو سوچنے سے روکنے کی کوشش کررہا ہے۔ جب نصابی کتب، میڈیا و اخبار انسانی احترام اور جذبوں کو پروان چڑھانے میں ناکام ہوں تو معاشرہ قصور وار نہیں ٹھہرایا جا سکتا
تعلیمی نظام میں وہ جادو ہے کہ اس سے معاشروں میں بگاڑ و سدھار پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اگر ذہن تنقیدی و تخلیقی نہ ہوں تو اس کا نقص فرد میں تلاش کرنے کے بجائے فرد کی تربیت کرنے والے اداروں میں تلاش کیا جائے ۔ چونکہ یہاں اس نظام کو کنٹرول کرنے والوں کا مقصد انکار کی قوت کو ختم کرنا ہے، تخلیقی سوچ کا گلا گھونٹنا ہے۔ اس لئے وہ اپنے اس مقصد کی حصول میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہوگئے ہیں۔ وگر نہ پاکستان کی معاشی ناہمواری اور لوگوں کی تنگدستی کی انتہا کے باوجود یہاں غضب کی خاموشی نہیں چھا جاتی، بلکہ لوگ مرکر بھی اپنے لئے خوشحالی لانے کی جدوجہد سے دستبردار نہیں ہوتے۔
دیو جیسی ریاستی مشینری، کاروباری فوج اور انسانی جانوں کی قیمت پر بننے والی ریاستی پالیسیوں کے خلاف بات کرنا سادہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی واقعی تبدیلی چاہتی ہے تو کھلی آنکھوں سے بلوچستان کی شہروں و گلیوں پر نظر دوڑائے۔ بلوچستان کی ’’پرشور خاموشی‘‘ کو سننے کی کوشش کرے اور ریاستی بیانیے کے بجائے حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کو معلوم پڑھ جاتی ہے کہ بلوچستان اپنے سپوتوں سے تبدیلی کی کیسی بھاری قیمت مانگ چکا ہے۔
چند دنوں پہلے اسلام آباد کے ’’برگر انقلابیوں‘‘ میں سے کسی کارکن کی ویڈیو سوشل میڈیا میں وائرل ہوگئی تھی، جس میں ایک معصوم کارکن کہہ رہے تھے کہ اگر پولیس ہم پر لاٹھی چارج کرے گی تو ہم کیسے انقلاب لا سکتے ہیں۔موصوف دیکھنے سے کسی یونیورسٹی کے پڑھے لکھے لگتے تھے، لیکن حقائق کو دیکھنے و تسلیم کرنے کا اس کا پیمانہ کم از کم مجھے مضحکہ خیز لگا۔ وہ اس لئے کہ سماجی تبدیلی جیسے عمل سے گزرنے کو ایک نوجوان کیسے اتنا سادہ سمجھ سکتا ہے، وہ بھی ایک ایسے ملک میں کہ جہاں ریاستی بیانیے کے برعکس بات کرنے والوں کے لئے قتل کے فتوے کھڑے کھڑے دیے جاتے ہیں،
یہ ایک فطری بات ہے کہ جاگیرداری و سرمایہ داری کی اس جدید ترین ڈیزائن، جسے جمہوریت کے خوش نما لبادے میں اوڑھ کرتیسری دنیا کے عوام کو جس طرح کنٹرول میں رکھا گیا ہے، اس کے خلاف اُٹھنے والی ہر آواز جو سمجھوتہ کرنے کے بجائے اپنی مقصد پر ڈٹے رہے اس طرح ہی غائب کردی جاتی ہے جس طرح کہ بلوچستان کی آواز کو لاپتہ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ بلوچستان شاہد ہے کہ یہاں پانی مانگنے والی کمسن ازگل، اور بجلی مانگنے والا کمسن لطیف بھی بندوق کے ذریعے خاموش کیے گئے ہیں۔
تعلیم عام کرنے والے صباء اور عابد آسکانی بھی مار دئیے جاتے ہیں ۔ سیاست ہر کسی کا حق ہے کا نعرہ لگانے والے شبیر، زاہد، دین محمد، زاکر، رمضان اور ہزاروں لاپتہ ہوجاتے ہیں۔ ان ہزاروں لاپتاؤں میں سے ہزاروں کی بازیابی مسخ شدہ لاشوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ یہ سب تجربات ایک نسل کو ہی نہیں بلکہ کئی نسلوں کو یہ سکھا نے کے لئے کافی ہیں کہ تبدیلی لانے کے لئے سخت جان ہونا پڑتا ہے۔زندگی کی حفاظت کرکے جدوجہد کرنا پڑتا ہے اور زندگی سے دستبرداری جیسی بدصورت عمل سے بھی مجبوراً گزرنا پڑتا ہے ۔ لاپتہ ہونے کا عذاب بھی سہنا پڑتا ہے۔
میرے لئے اس حقیقت کو تسلیم کرنا تلخ گھونٹ پینے سے بھی تلخ تر ہے کہ میرا ہمکار، میرے دوست شبیر بلوچ بھی اب ایک ’’مسنگ پرسن ‘‘ ہیں۔ بلوچستان میں ’’مسنگ پرسن‘‘ ہونے کا مطلب صرف لاپتہ ہونا نہیں بلکہ ہر پل اس انتظار میں مرنا ہے کہ کب اس ’’مسنگ پرسن‘‘ کی لاش کسی ویرانے سے مل جائے۔ یہ باتیں خیالی یا تصوراتی نہیں، بلکہ مجھ سمیت بہت سے لوگ لاپتہ بچوں کی خاندانوں سے یہ سُن چکے ہیں کہ اگر ہمارے بچوں کو مارا جا چکا ہے تو ان کی لاشیں ہمیں پہنچائی جائیں۔
افسوس کہ احساس قلمبند نہیں ہوتے، اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات ہے کہ ایسی باتیں اپنوں کی طرف سے بھی اَن سُنی ہو جاتی ہیں۔اگر لاپتہ لوگوں کی گمشدگی کا درد ایک اجتماعی درد ہوتا تو ھانی خود کو اپنے بابا کی ناکارہ بیٹی نہ کہتی۔ اور نہ ہی کوئی ماں اپنے بچے کی تصویر کو سینے سے لگائے بھرے بازاروں میں زور زور سے روتی۔
بلوچستان ہمیشہ سے شوریدہ رہا ہے، سیاسی کارکنوں کی بلوچستان میں جب شبیر، زاہد، زاکر، واحد سمیت ہزاروں لاپتاؤں کی گمشدگی پر بھی لکھاریوں، صحافیوں و ادیبوں کی خاموشی نہ ٹوٹے تو کئی لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ لاپتہ شبیر جیسے زندگی سے بھرپور نوجوان لیڈرکو، چیئرمین زاہد بلوچ کو، واحد، ڈاکٹر دین محمد، ذاکر مجید کو زندہ رہنا چاہیے ۔بلوچ لکھاری اور صحافی خاموش رہ کر اپنی ان ہستیوں کی زندگیوں کی حفاظت نہیں کرسکتے کہ ان کی زندگی سے ہی ہمارا قومی مستقبل جڑا ہے۔
گمشدہ لوگوں کے درد کو اب ایک اجتماعی درد بننا چاہیے، پنجابی، سندھی، پختون لکھاریوں کو بھی اس مسئلے کے خلاف مسلسل لکھنا اور بولنا چاہیے۔ بلوچستان کی سیاست کو زندہ اور برقرار رکھناہے تو سیاسی کارکنوں کی گمشدگی کے خلاف آواز بلند کرنا ہوگا۔ گمشدگی ایک سیاسی نہیں بلکہ انسانی مسئلہ ہے، اس کے خلاف ہر شخص کو نظریات و سیاسی وابستگیوں سے آگے بڑھ کردار ادا کرنا چاہیے ۔
♦