افسانہ
 نیلم احمد بشیر
نیلم احمد بشیر
میں نے اپنے کلینک میں داخل ہو کر ابھی اپنا سفید کوٹ پہنا ہی تھا کہ میری اسسٹنٹ نرس نے مجھ سے کہا۔
’’ڈاکٹر کل شام آپ کے جانے کے بعد ایک خاتون آپ سے ملنے آئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اسے اپائنٹمنٹ لے کر آنا چاہئے تھا‘‘ تو وہ بولی’’میں ڈاکٹر شریفہ کی بہت پرانی دوست ہوں۔ مجھے ان سے ضروری ملنا ہے۔‘‘
’’اچھا؟ کیا نام بتایا تھا اس نے؟‘‘ میں نے کچھ متجسس ہوکر پوچھا:۔
’’سعدیہ احمد‘‘ میری امریکن نرس نے نام کو صحیح انداز میں ادا کرنے کے لئے زبان پہ زور دے کر کہا۔ میں چونکہ خود مصری امریکن ہوں اس لئے مجھ یہ نام سمجھنے میں کوئی وقت محسوس نہیں ہوئی مگر نرس کے امریکن لب ولہجے میں نام کی ادائیگی پر میں ہولے سے مسکرادی۔
’’سعدیہ احمد، مگر مجھے تو کسی سعدیہ کا پتہ نہیں ہے۔‘‘ میں نے ذہن پر زور ڈال کرکہا۔
’’ڈاکٹر وہ یہ بیگ آپ کے لئے دے گئی ہے۔‘‘ نرس نے مجھے بیگ تھما دیا او رخود کام میں مصروف ہوگئی۔ میں نے بیگ کھولا تو جیسے یادوں کا ایک فوراہ اچھلا اور اچھل کر مجھے شرابور کرگیا۔ بیگ میں پڑی پرانی سی، مسلی اُدھڑی ہوئی کپڑے کی کالی گڑیا اپنی بے نور آنکھوں سے مجھے ٹکرٹکر دیکھے چلی جارہی تھی۔ سعدیہ کے ہاتھ میں یہ گڑیا میں نے بہت برس پہلے دیکھی تھی۔ جسے اس نے کیسے اب تک سنبھال رکھا تھا؟ میں دن بھر مریض اٹینڈ کرتے سعدیہ کے بارے میں ہی سوچتی رہی او رشام کو گھر جانے سے پہلے نرس سے پوچھا:۔
’’نمبر تو چھوڑا ہوگا اس نے؟‘‘
’’یس ڈاکٹر۔‘‘ جواب ملا۔
’’اچھا ٹھیک ہے اسے کہو، اتوار کو لنچ میرے ساتھ کرے۔ ٹھیک ایک بجے۔ میرا پتہ اسے سمجھا دینا۔‘‘ میں نے اپنی اسسٹنٹ کو ہدایات دیں او رخود گھر کی تیاری کرنے لگی۔ گھر جہاں میں اور میرا پوڈل کتا جیک رہتے تھے۔ میں نے دو ناکام شادیوں کے بعد تنہا رہنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ اس لئے اب میں صرف اپنے ساتھ بڑے سکون سے رہتی تھی۔ کبھی کبھی احساس ضرور ہوتا تھا کہ کوئی ساتھی ہونا چاہئے مگر جب ساتھی کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی ہی نہ ہوسکے تو پھر ایسے بندھن میں بندھے رہنے کا کوئی جواز ہی کہاں رہ جاتا ہے۔ ویسے بھی میں شادی میں محبت کی قائل تھی او رمحبت مجھے دونوں بارہی نصیب نہ ہوئی تھی۔
سعدیہ کو میں نے آج سے قریباً پچیس برس قبل امریکہ کا ویزادلوایا تھا او رپھر اس کے بعد میں اسے بھولی تو نہیں تھی مگر اس کی خیر خبر سے قطعاً آگاہ نہ رہ سکی تھی۔ مجھے نہیں پتہ تھا وہ اب کہاں ہے، کیا کرتی ہے، کیسی ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ میڈیکل پریکٹس کے اتنے مصروف کیرئیر کے دوران میں نے برسوں کسی او رطرف دھیان ہی نہ دیا تھا۔ میرے دونوں شوہروں کو بھی مجھ سے یہی شکایت رہی تھی کہ میں انہیں وقت اور توجہ نہیں دے پاتی مگر کیا کروں، مجھے لگا جیسے اس دنیا میں میری اولین او راہم ترین کمٹ منٹ صرف او رصرف اپنے کیرئیر سے ہے او راسے میں کبھی دوسرے درجے پر سمجھنے میں کامیاب نہیں ہوسکی ہوں۔
میں مصری والدین کی امریکی مصری بیٹی ہوں۔ امریکہ میں ہی پیدا ہوئی، پلی بڑھی مگر مجھے مصر سے، اہراموں کے علاوہ کوئی خاص دلچسپی پیدا نہ ہوسکی تھی۔ میرے مام اینڈ ڈیڈ امریکہ ہجرت تو کر آئے تھے مگر اپنے ملک کی یاد سے کبھی غافل نہ ہوسکے تھے۔ اکثر ہمارے کچن کاؤنٹر پر بڑی پرانی سی ریت گھڑی جسے وہ’’مقیاس الاساعت‘‘ کہتے تھے، کو الٹتے پلٹتے رہتے یوں جیسے وہ وقت میں دوبارہ واپس جانا چاہتے ہوں۔ میرے ڈیڈ کہتے ہیں’’دریائے نیل کے کنارے آباد صدیوں پرانی تہذیب ، ہم مصریوں کے ڈی این اے میں سرایت کرجاتی ہے۔ ہم اس کے سحر او رکشش سے کبھی آزاد نہیں ہوسکتے۔ او رکچھ نہیں تو یہ تمہیں بلائے گی او رتم دوڑتی چلی جاؤ گی۔‘‘ وہ ہمارے نیویارک سٹی کے سکائی سکریپربلڈنگ کے اپارٹمنٹ کی کھڑکی میں سجے ننھے ننھے اہرام مصر کے ماڈل فگرز کو ہولے سے تھپتھپاتے او رمسکرا کر مجھے چھیڑتے رہتے۔
’’مام ڈیڈ میں نیویارک کی باسی ہوں۔ بلندو بالا عمارتیں دیکھنے کی عادی۔ مجھے یہ پرانی پرانی تکون عمارتیں بھلا کیوں کر اپنی جانب کھینچ سکتی ہیں؟‘‘
پھر ایک روز میں نے اخبار میں پڑھا کہ اس زمانے کے مشہور ادیب، فلسفی، مفکر جاں پال سارترے او ران کی ساتھی سیمون ڈی بووئیر مصر کے کسی قدیم گاؤں کی سیر کو گئے ہیں۔ یہ ساٹھ کے عشرے کے آخری سالوں کی بات ہے۔ ہم سب نوجوان سارترے کی تحریروں او رافکار کے مداح ہونے کی وجہ سے ان کی ہربات اور ایکٹیوٹی کو صحیح او رجائز مانتے تھے۔ اخبار کی سٹوری کافی دلچسپ تھی۔ لکھا تھا کہ جب وہ دونوں گاؤں پہنچے تو مقامی طلباء آوازیں لگاتے ان کی کار کے پیچھے دوڑتے چلے گئے۔
مزے کی بات یہ بھی تھی کہ یونیورسٹی والوں نے گاؤں کے سیدھے سادے کسانوں کو ’’وجودیت‘‘ کے فلسفے سے متعلق بہت مشکل مشکل سوال دے دئیے گئے تاکہ وہ سارترے اور سیمون سے ان کے جواب طلب کریں۔ سارترے تو کتاب لکھ چکے تھے کہ ’’وجودیت ہی انسانیت ہے‘‘ انہوں نے بھلا کسانوں کے سوالوں کا خاک جواب دینا تھا۔ بہرحال کئی روز تک میڈیکل کالج میں یہ موضوع زیر بحث رہا کہ سارترے کے وزٹ کا مقصد کیا تھا او راس نے اس سے حاصل کیا کیا؟ میں اور میرے چند نوجوان ساتھی ڈاکٹروں نے سارترے کی محبت او رتقلید میں ہی گریجوایشن کرنے کے بعد فیصلہ کرلیا کہ ہم لوگ مصر کے کسی گاؤں جاکر ضرور کام کریں گے۔ وہاں کے لوگوں کو طبی سہولیات فراہم کریں گے۔ ساتھ ساتھ مصر کے بارے میں تاریخی او رتہذیبی آگاہی بھی حاصل کریں گے۔ لگتا تھا مام ڈیڈ کی بات پوری ہونے جارہی ہے۔
ہم میں سے چند نوجوان ڈاکٹروں نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ایک ویمن ڈویلپمنٹ پروگرام میں شمولیت اختیار کی او ریوں بالآخر مصر پہنچ گئے۔ جانے سے پہلے میرے مصری والدین مجھے پیار سے چھیڑ چھیڑ کر اکثر یاد دلاتے رہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بالآخر مصر اوراس میں بہنے والا نیل مجھے ایک بار ضرور اپنی طرف بلائے گا اور میں جاؤں گی۔ میں ان کی بات سن کر ہنس دیتی رہی مگر دل میں یہ خیال ضرور جاگا کہ کہیں واقعی اس میں کوئی صداقت ہی نہ ہو۔ میں یہی کہتی رہی کہ میں تو اپنی استاد سارترے اور اس کی ساتھی سیمون کے نقش قدم پر چل رہی ہوں۔ ان کے تجسس کو کھوجنے وہاں جارہی ہوں ورنہ میرا مصر سے کیا لینا دینا۔
سعدیہ احمد کے بارے میں سوچتی سوچتی میں خیالوں میں بہت آگے نکل گئی۔ بالآخر اتوار کا دن آہی گیا۔ میں نے سوچا لائٹ لنچ کریں تو اچھا رہے گا۔ پاسٹاوِدٹماٹر ساس او رسلاد ٹھیک رہے گا۔ میرے ہاتھ تیزی سے حرکت کرنے لگے اور میرے آگے ماضی کی فلم سی چلنے لگی۔ ریت گھڑی اب بھی میرے کچن کاؤنٹر پر رکھی رہتی تھی۔ او رکسی پرانی سہیلی کی طرح زمانے کے ہر دور میں ہمیشہ میرے ساتھ رہی تھی۔ ریت کے ننھے ننھے بھورے ذرے شیشے کے پیمانے میں پھسل پھسل کر نیچے کو گرتے جارہے تھے او روقت کے لمحے پھڑ پھڑا کر فضا میں تحلیل ہورہے تھے۔ مجھے یاد آیا میں بچپن میں اس ریت گھڑی کا تماشہ گھنٹوں بیٹھی دیکھتی رہتی تو میرے ڈیڈ پیار سے میرا سر سہلا کر کہتے’’بیٹی وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اس کی قدر کرنی چاہئے۔ یہ ہمیشہ رواں دواں رہتا ہے۔ واپس کبھی نہیں لوٹتا۔‘‘ میں کافی کامگ ہاتھ میں تھام کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ نیویارک شہر میں زندگی بھاگتی چلی جارہی تھی۔ آگے ہی آگے۔۔۔ تیز ہی تیز۔۔۔
وہ دن یاد آگیا جب میں او رمیری دوست ڈاکٹر للی سٹون مصر جاپہنچے تھے۔ ہماری منزل مصر کے بڑے شہر اسوان کے قریب بسنے والا گاؤں نوبین تھا۔ صحرا کی زرد ریت کے قالین پہ بچھے اس قدیم گاؤں کے آس پاس تاریخ تہہ درتہہ سانس لیتی محسوس ہوتی تھی۔ ہم اسوان سے چلے تو نیل کی لہروں پہ بہنے والی ایک کشتی نے ہمیں تین گھنٹے بعد نوبین پہنچادیا۔ راہ میں نیل سے میں نے بہت سی باتیں کیں۔ اپنے مام ڈیڈ کا سلام پہنچایا تو نیل مسکراتا مسکراتا اور نیلا ہوتا چلا گیا۔
اگلے روز ہمیں بطور آبزرور ایک ایسی جگہ لے جایا گیا جہاں گاؤں کی جواں سال بچیوں کے اجتماعی ختنے ہونا تھے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں صرف دیکھنے کی اورنوٹس بنانے کی اجازت ہے۔ کسی قسم کی طبی مداخلت کی نہیں۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کیا دیکھنے جا رہے ہیں۔ تہذیب وتمدن کے معاملے ایسے ہوتے ہیں جن میں سوال جواب کی گنجائش ضروری سمجھی نہیں جاتی۔ ہمیں ہماری کو آرڈی نیٹر نے ایک معلوماتی بروشردیا جس میں کچھ ایسا لکھا تھا کہ یہ رواج صرف مسلمانوں میں ہی سمجھ لینا درست نہیں ہے۔ یہ ایک قدیم رسم ہے جس کے ڈانڈے تاریخ میں بہت دور تک جاملتے ہیں۔ قبل از مسیح زمانوں میں او رفرعونوں کے دور میں بھی عورت کے ختنے کر دئیے جاتے ہیں۔ برآمد ہونے والی کئی ممیاں(حنوط شدہ لاشیں) اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ تب بھی یہ عمل ہوتا تھا۔ کئی لاشوں میں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خواتین کے نازک حصے میں ایک نتھ نما چیز ڈال دی جاتی تھی۔ اسی طرح یورپ کے مرد پندرھویں صدی تک جنگوں پہ روانہ ہونے سے قبل اپنی خواتین کو آہنی بیلٹ پہنا کر قفل بند کرجاتے تھے تاکہ ان کی غیر حاضری میں وہ صابر اور وفادار رہ سکیں۔ آج کے افریقی ممالک میں جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، ملاؤں کے اس اصرار پر یہ پریکٹس جاری وساری رکھی جاتی ہے کہ عورت کا تقویٰ او رپاکبازی برقرار رکھنے کے لئے ان کے ساتھ ایسا ہی کرنا ضروری ہے۔ ان باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے آج بھی ہمارے ہاں کے مرد اس کے حامی ہیں اور ایسی لڑکیوں کے رشتوں کو ترجیح اور فوقیت دیتے ہیں جن کے ختنے ہوچکے ہوں۔ عورت کے وقار کے لئے یہ ضروری ہے ورنہ زندگی میں اسے نہ محبت ملتی ہے نہ عزت۔
ہماری معاون مصری خاتون نے معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا۔ یہ سب سن کر میری او رمیری دوست للی کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہمیں گاؤں کے ایک رہائشی علاقے میں چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں کی قطار کے پچھواڑے لے جایا گیا۔ شدید گرمی کا موسم تھا۔ مٹی، گارے اور جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے جھونپڑے گرم ہوا کے تھپیڑوں کا مقابلہ کرتے ادھر سے ادھر جھولتے دکھائی دیتے تھے۔ لمبے لمبے چوغوں میں ملبوس گاؤں کے بڑے بوڑھے کھجوروں کے جھنڈتلے بیٹھے سکون سے حقہ نوشی کررہے تھے او ربچوں کے غول قریبی کیلے کے کھیت میں گھسے، کھیل کود سے جی بہلارہے تھے۔ کبھی کبھی وہ ہم غیر ملکیوں کو پر اشتیاق نگاہوں سے تکتے او رکبھی قطعاً نظر انداز کرکے اپنے کھیل میں مشغول ہوجاتے تھے۔
ایک جھونپڑی سے کچھ آوازیں آرہی تھیں۔ اگر خوف اور دہشت کی کوئی آواز ہوتی ہے تو وہ وہی تھی۔ انہیں رونا تو نہیں کہا جاسکتا بس ایک آہوں، سسکیوں اور چیخوں کا مسلسل شور تھا جس کی وجہ سے کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔
’’یہ کیا ہورہا ہے؟‘‘ میں نے سہمی ہوئی آواز میں کوآرڈی نیٹر سے پوچھا حالانکہ مجھے پتہ تھا کہ یہ ان لڑکیوں کی آوازیں ہیں جن کی باری آنے والی تھی۔ مجھے کوئی جواب نہ ملا او رہمیں کہا گیا کہ ہم چاہیں تو اپنے نوٹس تیار کرسکتی ہیں ہمیں اس کی اجازت ہے۔
دروازہ کھلا اور دس سے پندرہ سال تک کی آبنوسی جلد والی ہرنیوں جیسی آنکھوں والی معصوم نوجوان لڑکیاں ایک کے بعد ایک لاکرکھڑی کردی گئیں۔ ایک کھلی جگہ پر بیٹھ کر پتھروں پہ استرے او ربلیڈگھس کر تیز کرنے والی بوڑھی عورتیں خوشی سے ایک دوسرے سے باتیں کئے جارہی تھی۔ عنقریب انہیں اپنی محنت کا اچھا معاوضہ ملنا تھا جس کی وجہ سے ان کی رگوں میں لہو گرم ہوکر دوڑرہا تھا۔ لرزتی ہوئی لڑکیوں کے ہاتھ میں ایک ایک کپڑے کی گڑیا او رکھانے پینے کی چیزوں کا بیگ تھا جسے انہوں نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔
اُسی لمحے گرم ہوا مجھے او رزیادہ گرم لگنے لگی۔ میں نے اپنے ماتھے پر آتے ہوئے پسینے کے قطروں کو زمین پر ٹپکتے دیکھ کر سوچا۔۔۔ کم ازکم یہ سرخ تو نہیں تھے مگر پھر۔۔۔ دوسرے ہی لمحے سرخ لہو کے دریا کو مجھے دیکھنا تھا۔
دو بوڑھی چڑیلیں آگے بڑھیں اور انہوں نے بارہ تیرہ سالہ ہاجرہ کو ٹانگوں سے پکڑلیا۔ دوسری دو نے اس کے بازوؤں کوجکڑلیا۔ اب وہ لکڑی کے ایک اونچے تختے پہ لیٹی کسمسارہی تھی۔ ’’بے وقوف لڑکی، ہم تجھے نہ چھوڑیں گے۔ خوامخواہ زور لگائے گی تو تیرے کو لہے کی ہڈیاں چٹخ جائیں گی۔‘‘ ایک طنزیہ ہنسی کے بیچ بولی۔ ہماری مترجم ہمیں بتانے لگی کہ کیا کہہ رہی ہیں۔ ایک بڑھیا نے جو بہت ہی مضبوط کاٹھی رکھتی تھی۔ آگے بڑھ کر حاجرہ کو ایک دم سے برہنہ کردیا۔ میں نے نظریں گھما کر دور دیکھا۔ پس منظر میں کھڑے پرانے مضبوط طاقتور اہرام کی تکون اپنی جگہ پر جامد وقائم تھی اور اب ایک یہ تکون میرے سامنے تھی۔ بے وقعت، بے بس او رکمزور جسے زمانہ کدالیں لے کر تہس نہس کرنے کے درپے تھا۔
دوسرے ہی لمحے ایک بڑھیا جو شاید اس آپریشن کی سرجن سمجھی جاتی تھیں بلیڈ لے کر آگے بڑھی۔ حاجرہ کی ٹانگیں چیر کر اس کے جسم کے نازک ترین حصے کو یوں بے دردی سے کتر ڈالا جیسے وہ کوئی زائد پالتو شے ہو۔ لڑکی کی چیخوں سے آسمان لرز اٹھا۔ آئی کین ناٹ بیلیو۔ اینستھیزیا کے بغیر اتنا سنجیدہ آپریشن، اتنی بربریت؟ للی غصے او رغم سے کانپنے لگی۔
’’میں دیکھتی ہوں پیشنٹ کو‘‘ اس سے رہا نہ گیا اور وہ آگے بڑے کر لڑکی کو چیک کرنے لگی مگر ہماری نمایندہ عورت نے ہمیں ہاتھ سے روک دیا او ربولی’’آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو یہاں کے پرانے رسم ورواج میں مداخلت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔’’ڈاکٹرز، یاد رکھیں، آپ صرف آبزرورہیں او رکچھ نہیں۔‘‘ ہم دونوں سہم کر پیچھے ہٹ گئیں اور حاجرہ کی صحت مند گداز ٹانگوں پر سرسراتے ہوئے خون کی لکیروں سے بنے ہوئے نقش ونگار کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگیں۔ سرجن بڑھیا نے ٹانگوں کو ایک دوسرے سے جدا کرکے ان کے بیچوں بیچ، حیات کو جنم دینے والے روزن میں لکڑی کا ایک گول ٹکڑا پھنسا کر زخمو ں پر نمک چھڑک دیا۔ ایک دوسری عورت آگے بڑھی اور اس نے زخمی عضو کے پامال حصے میں جھاڑیوں سے نوچے ہوئے چند کانٹے پھنسادئیے۔ سب بڑی مستعدی سے اپنا کام کررہی تھیں۔
’’یہ کیا او رکیوں؟‘‘ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ للی نے سینے پر کراس کا نشان بنا کر آنکھیں بند کرلیں۔ شاید یہ سب کچھ اس کے لئے بہت زیادہ تھا۔
’’نمک انفکشن روکے گا او رلکڑی کا گول ٹکڑا ماس کو آپس میں جڑنے نہیں دے گا۔ آخر ہمیں ان کی جسمانی حاجات کا بھی تو خیال رکھنا ہوتا ہے۔ کانٹے بھی ماس کو جدارکھنے کے لئے بہت موزوں رہتے ہیں۔‘ ہماری معاون نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔
میں نے اس دنیا میں ایسے کسی چمنستان محبت کے بارے میں نہ دیکھا نہ سنا تھا جہاں پاکیزہ، نرم ونازک، حساس پھولوں کی پنکھڑیوں کو کانٹوں کی مہربانی کا مرہون منت ہونا پڑتا ہو۔
ایک کے بعد ایک سبھی لڑکیاں اسی طرح لائی گئیں اور وہی عمل دہرایا گیا۔ چیخوں او رونے کی آوازوں سے ماحول سوگوار ہوتا چلا گیا۔
’’خاک خیال ہے ان بڈھی چڑیلوں کو ان لڑکیوں کا، سب جھوٹ ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کم بخت عورتیں بچپن میں اپنے ساتھ کئے گئے اس ظلم کا بدلہ آج ان لڑکیوں سے لے کر لذت حاصل کررہی ہیں۔‘‘ للی کا چہرہ غصے سے لال ہوگیا۔ اس نے بمشکل ایک ابکائی کو اوپر آنے سے روکتے ہوئے کہا۔
’’یہاں صدیوں سے ایسا ہی ہوتا چلا آرہا ہے ڈاکٹر لیڈی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا۔ہم شوہروں کی خوشی او رپاکبازی کے تقاضے کی خاطر یہ سب آرام سے بھگت لیتی ہیں۔‘‘ ایک بڑھیا بولی۔
’’لیکن۔۔۔ لیکن اب یہ ٹھیک کیسے ہوں گی؟‘‘ میں نے گھگھیا کر سوال کیا۔
’’ہم چالیس دن ان کی ٹانگیں باندھ کر رکھیں گے۔ اللہ کے حکم سے سب ٹھیک ہوجائے گا۔ لڑکیوں کا’’طہارہ‘‘ ہوجائے تو انہیں اچھے بر بھی مل جاتے ہیں۔ ہر عورت کو ایک دن ماں بننا ہے اور جس عورت کے ختنے نہ ہوئے ہوں وہ ماں کہلانے کی حقدار نہیں سمجھی جاتی۔ آخر ماں سفلی جذبات او ر جسمانی خواہشات والی تو نہیں ہوسکتی۔ یہ اس کی عزت کا سوال ہے۔‘‘
کام ختم ہوجانے کے بعد ایک بڑھیا سگریٹ سلگاکر زمین پر بیٹھ گئی اس نے اپنے سر سے ٹوپی نما کپڑے کو ہٹایا اور پھر دوبارہ سیٹ کرکے جمادیا۔ تیز شوخ رنگوں کے ملبوس پہنے زخمی لڑکیاں سسکتی، بلکتی رہیں۔ یوں جیسے وہ خوبصورت تیتریوں کے پُرکٹے وجود ہوں جنہیں اڑنے کی صلاحیت سے محروم کردیا گیا ہے۔
’’ڈاکٹر مس، ہماری عورتوں کے مقدر میں تین غم لکھے ہوتے ہیں۔ تین غم زندگی میں ہمیں ضرور ملتے ہیں۔‘‘ بڑھیا نے دھوئیں کا مرغولہ اڑاتے ہوئے کہا۔
ہماری گائیڈ نے ہمیں پھر انگریزی میں ترجمہ کرکے بتایا۔ ہم نے سوالیہ نگاہوں سے بڑھیا کی طرف دیکھا۔
’’پہلا غم تو آج آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ لڑکی جب جوانی کی حدود میں قدم رکھنے لگتی ہے تو اسے پہلی بار کاٹا جاتا ہے۔ دوسراغم وہ کٹنا ہے جو اسے شادی سے پہلے پھر برداشت کرنا پڑتا ہے۔‘‘ وہ بغیر کسی جذبے کے بولتی چلی گئی۔
’’کیا مطلب؟‘‘ للی نے سمجھ میں نہ آنے والے انداز میں پوچھا:۔
’’اگر شادی سے پہلے اسے کاٹ کر وسعت نہ پیدا کی جائے تو شوہر خود چھری لے کر۔۔۔ بڑھیا نے فقرہ آدھا چھوڑ دیا۔۔۔ اس لئے ہم لڑکیوں کو خود ہی کاٹ دیتے ہیں۔ آخر شوہر کی دقت کا بھی تو خیال رکھنا ہوتا ہے۔‘‘ ہم دونوں کا سانس اُوپر کا اُوپر او رنیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔
’’تیسرا غم؟‘‘ للی نے تھوک نگلتے ہوئے بڑی مشکل سے پوچھا:۔
’’تیسرا غم ہماری عورت کو جب ملتا ہے جب اسے بچے کو جنم دینا ہوتا ہے۔ کئی بار پہلا زخم ٹھیک سے نہ بھرنے کی وجہ سے رہگزر تنگ ہوجاتی ہے لہٰذا ہم اسے بچے کی ولادت سے پہلے ایک بار پھر کاٹ دیتے ہیں۔‘‘
’’اومائی گاڈ‘‘ للی او رمیرے منہ سے بیک وقت نکلا۔
’’لیکن یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ عورت کے لئے محبت او رایک ہوجانے کے فطری جذبے کی میٹھی طمانیت، تسکین، اتنا بڑا جرم کیوں قرار پاتی ہے۔‘‘ ہم نے اپنی معاون میڈیکل نمائندہ عورت سے جھنجھلا کر پوچھا:۔
’’یہ اس لئے کیا جاتا ہے کہ عورتوں میں کوئی سفلی جذبات پیدا ہی نہ ہوں۔ ان کی حسیات مرجائیں۔۔۔ اور وہ سیدھی راہ پہ چل سکیں۔‘‘ جواب ملا۔
ہمارے اردگرد بے جان گڑیوں کا ایک ڈھیر تھا جسے زندگی بسر کرنے کی خواہش اور صلاحیت سے محروم کردیا گیا تھا۔
’’یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن آخر کہاں پڑی سورہی ہے؟‘‘ میں نے الفاظ چباتے ہوئے للی کے کان میں سرگوشی کی۔ اسی لمحے بارہ تیرہ برس کی ایک دبلی پتلی لڑکی نہ جانے کہاں سے بھاگتی ہوئی آئی اور آکر میری ٹانگوں سے چمٹ گئی ’’ڈاکٹر، ہیلپ۔۔۔می پلیزسیو می۔‘‘ وہ باربار چیخ رہی تھی۔
’’ارے یہ کم بخت نہ جانے کہاں چھپی ہوئی تھی۔ ہم تو اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی تھیں۔ دو بڑی بوڑھیاں اٹھیں اور اسے دبوچ کر ذبح گاہ کی طرف لے جانے لگیں۔
’’سعدیہ۔۔۔ سعدیہ۔۔۔ میری بچی۔۔۔‘‘ ایک عورت جو مشکل سے اس کی ماں لگتی تھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی آئی اور ہمیں دیکھ کر بولی’’ڈاکٹر میری بچی کو بچالیں میں نہیں چاہتی کہ میری بچی کے ساتھ یہ ظلم ہو‘‘ مجھے کچھ کچھ مصری زبان کی شُد بد تو تھی ہی مگر نہ جانے کیسے میں اس کی ساری بات سمجھ گئی۔ یہ بات میرے لئے بہت حیرت انگیز او رخوش آئند تھی کہ کوئی ایسی عورت بھی تھی جو اس رواج کو غلط سمجھ کر اپنی بچی کو بچالینا چاہتی تھی۔ مجھے نہ جانے کیا سوجھی۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، ننھی سعدیہ کا ہاتھ تھا مااور اسے دوڑاتی ہوئی اپنے رہائشی کمپاؤنڈ کی طرف لے بھاگی۔ للی نے بھی ہمارا ساتھ دیا۔ ہم ہر قیمت پر اسے بچالینا چاہتی تھیں۔ سعدیہ یوں لرز اور ہانپ رہی تھی جیسے شکاری کے تیرسے بچ نکلنے والی کوئی ہرنی ہو۔ کمپاؤنڈ پہنچتے ہی میں نے کمرے کا دروازہ بند کرلیا۔ عورتیں دروازہ پیٹتی رہیں مگر ہم اسے انسانی حقوق کی بنیاد پر اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں ہمیں اس کی اجازت دی جائے۔
پھر سعدیہ میرے ساتھ امریکہ کیسے آئی یہ الگ داستان ہے۔ یہاں آکر میں نے اسے ایک فوسٹر ہوم میں بھجوادیا جہاں لاوارث بچوں کی کےئر کی جاتی ہے۔ پھر وقت گزرتا چلا گیا میرا اور سعدیہ کا آپس میں کوئی رابطہ بھی نہ رہا۔ میں اسے تقریباً بھول چکی تھی اور آج وہ مجھ سے ملنے میرے گھر آرہی تھی۔ مجھے گزرے ہوئے سب ہی واقعات یاد آنے لگے تھے اور حیرت ہورہی تھی کہ اتنے سالوں سے وہ اور میں ایک دوسرے سے کٹے کیوں رہے تھے۔
عین ایک بجے دروازے کی گھنٹی بجی۔ میرا پالتو کتا پوڈل جیک دم ہلاتا دروازے کے پاس جاکھڑا ہوا۔ اسے ہمیشہ ہی گھنٹی کی آواز چوکنا کردیا کرتی تھی۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ ایک کیک کا ڈبہ میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ پھر ایک سرخ گلابوں کا گلدستہ نظر آیا جس کے پیچھے کوئی چہرہ تھا جسے میں فوری طور پر دیکھ نہ سکی تھی۔ پھول ہٹائے گئے تو میں نے دیکھا ایک سیاہ گلاب میری آنکھوں کے سامنے دمک رہا تھا۔
‘‘ہیلو ڈاکٹر مس۔‘‘ اس نے مجھے اسی طرح پکارا جیسے وہ بچپن میں پکارا کرتی تھی۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ برسوں بعد میں اسے دیکھ رہی تھی۔
’’کیسی ہو مائی ڈئیر سعدیہ۔۔۔ ارے بڑی خوبصورت ہوگئی ہو۔ کیا بات ہے؟‘‘ وہ مجھ سے پیار سے لپٹ گئی تو میں نے بھی محبت او رگرمجوشی سے اسے بھینچ لیا۔ میری اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی مگر اس وقت نہ جانے کیوں وہ مجھے اپنی بیٹی سی لگی۔
’’آپ بتائیں۔ ٹھیک تو ہیں؟ میں آپ کو ہمیشہ مس کرتی رہی، ڈھونڈتی رہی۔ بڑی مشکل سے انٹرنیٹ کے ذریعے میں نے آپ کا پتہ لگایا ہے۔‘‘ وہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے میرے گھر کو بغور دیکھتے ہوئے بولی۔
’’ہاں میں نے بھی تو ٹِک کے کسی سٹیٹ میں کام نہیں کیا۔ کبھی یہاں تو کبھی وہاں او رایک سال تو میں پھر سے مصر میں بھی کام کرنے چلی گئی تھی۔‘‘ میں نے اسے ہنس کر اپنی پیشہ وارانہ زندگی کی مصروفیات کے بارے میں بتایا۔ میری مصری اب بھی کچھ اتنی خاص نہیں تھی مگر سعدیہ کی انگریزی مکمل امریکن تھی۔ ہمیں ایک دوسرے کی بات سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہورہی تھی ہم دونوں باتیں کرنے لگیں۔
’’ڈاکٹر مس۔ آپ نے تو میری زندگی ہی بدل دی۔ مجھے امریکہ کی سپانسر شپ دلوائی۔ میری محسن ہیں آپ۔‘‘ وہ پیارسے میرا ہاتھ تھام کر تقریباً میرے گھنٹوں میں جھک گئی۔
’’ارے مجھے تو خود کچھ نہیں پتہ چلا کہ وہ سب ہوا کیسے تھا؟ بس ہوگیا۔ شکرہے میں تمہارے کام آسکی۔‘‘ میں نے اسے زمین پر سے اٹھاتے ہوئے کہا۔
’’ڈاکٹر مس یہ وہی ریت گھڑی ہے نا جو تب بھی آپ کے کمرے میں ہوتی تھی۔‘‘اس نے میرے ماں باپ کی نشانی ’’مقیاس الساعت‘‘ کو ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ریت کے ذرے حسب معمول لمحہ لمحہ بن کر گر رہے تھے او روقت آگے ہی آگے کو چلتا جارہا تھا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور اسے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اسے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتایا او رپھر اس سے سوال کیا۔
’’مائی ڈےئر تم کیا کرتی رہی اتنے سال؟ کچھ اپنی کہو۔ کہاں رہیں ، کیا کیا؟‘‘
’’ڈاکٹر مس۔۔۔ میں نے خوب پڑھائی کی، فلسفہ کی تعلیم حاصل کی۔‘‘ اس نے فخر یہ انداز میں بتایا۔
’’فلسفہ؟۔۔۔ واہ بھئی۔۔۔ ویری امپریسو۔۔۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔۔۔‘‘ میں نے اسے شاباش دیتے ہوئے کہا۔
’’یہ فلسفہ ہی تو مجھے تمہارے گاؤں لے گیا تھا۔۔۔‘‘ میں نے ہنس کر راز افشاء کیا۔
’’واقعی ڈاکٹر مس؟ وہ کیسے؟‘‘ اس نے پوچھا۔
’’دراصل وہ زمانہ بڑا آئیڈیلزم کا زمانہ تھا۔ ہم نے سنا کہ ژاں پال سارترے فلسفۂ وجودیت کے پرچارک مصر کے کسی گاؤں کے وزِٹ کو گئے ہیں تو بس ہم نے بھی سامان باندھ لیا۔۔۔ یونو۔۔۔ نوجوانی او رطالب علمی میں یہ سب بہت بھلا معلوم ہوتا ہے۔‘‘ میں نے پاسٹا میں ساس مکس کرتے ہوئے کہا۔ او رخود سلاد کی پلیٹ اپنے آگے کھسکائی۔
ڈاکٹر مس۔۔۔ سارترے تو مجھے بھی بہت پسند رہا ہے۔۔۔ کیسا عجب اتفاق ہے اورفلسفۂ وجودیت کی اہمیت کون کبھی انکار کرسکا ہے۔ انسانی فری ول یعنی اپنی مرضی او رانتخاب کی آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔۔۔ سوسائٹی کے فریم ورک میں رہ کر اپنی منشاء کے مطابق انفرادی حیثیت سے زندگی کرنا۔۔۔ بہت اعلیٰ اور برتر قسم کی آئیڈیالوجی ہے۔‘‘ وہ بولتی چلی گئی۔
’’ارے بھئی تم تو پوری فلاسفر بن گئی ہو۔۔۔ بہرحال میں بہت خوش ہوں کہ تم نے زندگی کو اتنی بہادری اوراستقامت سے برتا ہے۔ میری کوشش رائیگاں نہیں گئی۔ میں نے کافی بناتے ہوئے اس سے کہا۔
ہم دونوں دیر تک اس زمانے کی باتیں کرتے رہے اور ساتھ ہی گاؤں کو یاد کرتے رہے۔
’’ڈاکٹر مس۔ میں اتنی جلدی میں وہاں سے نکلی تھی کہ کسی کو رخصت سے مل بھی نہ سکی تھی۔‘‘ اس نے خلا میں گھورتے ہوئے جواب دیا۔
’’کس کوملنا تھا۔ تمہاری اماں تو بعد میں آگئی تھیں نا۔۔۔‘‘ مجھے پتہ تھا کہ اس کا اپنی ماں کے سوا او رکوئی نہ تھا۔
’’ہاں ماں تو آگئی تھی مگر ظہور۔۔۔ پیچھے رہ گیا تھا۔‘‘
’’ظہور؟‘‘ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا:۔
’’وہ بچپن سے میرا منگیتر تھا۔ مجھے تو کچھ خاص سمجھ نہ تھی مگر وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ یہ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا۔‘‘ اس نے شرمیلی سی مسکراہٹ سے کہا:۔
’’اچھا؟‘‘ او ویری سوری۔۔۔ میں نے تو پھر اچھا نہیں کیا۔ ظہور سے سعدیہ کو چھین لیا۔ وہ تو مجھے بہت کوستارہا ہوگا۔‘‘ میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ سعدیہ مسکرادی۔
’’مس جب وہ جوان ہوا تو مجھے ڈھونڈتا ہوا امریکہ آگیا۔ مجھے سے ملا اور۔۔۔‘‘
’’ارے واقعی‘‘ میں نے اس کی بات بیچ میں سے ہی اچک لی۔’’پھر کیا ہوا؟‘‘
’’ہونا کیا تھا۔۔۔ پھر ہم نے شادی کرلی۔۔۔ اب ہمارے دو بچے ہیں۔‘‘ وہ مجھے بتاتی گئی اوراس کا چہرہ خوشی سے گلنار ہوتا چلا گیا۔
میں نے اسے اٹھ کر گلے سے لگالیا۔تمہیں ایک مکمل اور بھر پور زندگی گزارتے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے سعدیہ۔ ایک بھگوڑی لڑکی کو منزل بھی ملی اور مسرت بھی۔۔۔ گریٹ۔۔۔ اور کیا چاہئے ہوتا ہے زندگی میں، یو آر اے ونر۔۔۔۔
’’محبت چاہئے ہوتی ہے۔۔۔ بہت سی محبت، ماں۔‘‘ یکدم سعدیہ اٹھی اور میرا ہاتھ تھام کر بولی۔’’ مجھے اپنے شوہر کی محبت سے زیادہ کچھ عزیز نہیں ہے۔‘‘
’’ہاں تو وہ تم سے محبت تو کرتا ہی ہے نا۔۔۔ آخر تمہاری محبت کی شادی ہے۔۔۔‘‘ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا’’وہ تو ہے مگر۔۔۔‘‘ اس نے بات بیچ میں چھوڑ دی۔
’’ڈاکٹر مس۔۔۔ وہ مجھ پہ شک کرتا ہے۔۔۔ اسے میری محبت اور وفاداری کا یقین نہیں آتا۔‘‘۔۔۔ سعدیہ نے آنسو بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھ کرکہا:۔
’’یہ کیا بات ہوئی۔۔۔ کیوں نہیں یقین آتا اسے‘‘ میں نے حیران ہوکر پوچھا۔
’’اس لئے کہ میرا وجود سلامت ہے۔۔۔ اُسے کُتراجو نہیں گیا تھا۔‘‘ سعدیہ کی آنکھوں سے جھر جھر آنسو بہنے لگے مجھے لگا جیسے نیویارک سٹی کی سب سے بلند بلڈنگ پر کسی طیارے نے حملہ کردیا ہو۔ لوگ آگ میں جلنے بھننے لگے ہوں۔
’’اوہ مائی گاڈ۔۔۔ آج امریکہ میں رہتے ہوئے۔۔۔ اتنے بہت سے برسوں بعد بھی ظہور کی سوچ تبدیل نہیں ہوئی۔۔۔ اسے پتہ نہیں کہ ادھوری عورت اور مکمل عورت میں کچھ فرق ہوتا ہے؟ کیا اسے تم سے اپنی محبت کی شادی کرکے خوشی نہیں ہوئی کہ میری ہم سفر ہر لحاظ سے پوری، نیچرل او رپر اعتماد ہے۔۔۔ وہ کسی بربریت کے نتیجے میں احساس کمتری اور خوف کا شکار نہیں ہوئی۔‘‘ مجھے غصہ آنے لگا۔
’’یہ کیسی بات بتائی ہے تم نے؟‘‘ میں بولتی چلی گئی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا۔
’’ماں میں تمہارے پاس ایک التجالے کر آئی ہوں۔‘‘ یکایک سعدیہ کا لہجہ بہت جذباتی ہوگیا۔
’’آپ بہت بڑی سرجن ہیں۔ آپ ہی میری مشکل کو سمجھ سکتی ہیں۔ پلیز۔۔۔ پلیز مجھے اُن۔۔۔ عورتوں جیسا ہی بنادیں جو میرے گاؤں میں بستی ہیں۔ میں مختلف نہیں ہونا چاہتی۔ پلیز مجھے۔۔۔‘‘ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی’’میرا ظہور تبھی مجھ سے پیار کرے گا او رمجھ پاکباز سمجھے گا۔۔۔‘‘
غصے کے مارے پاسٹا کے پلیٹ میری ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ میں فرطِ جذبات سے اپنی کرسی سے کھڑی ہوگئی۔
’’کیا کہہ رہی ہو تم بے وقوف لڑکی۔۔۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہوگیا؟ یہ کیا خرافات ہے؟‘‘
’’ماں، آپ میری ماں ہی تو ہیں۔۔۔ آپ ہی میرا مسئلہ سمجھ سکتی ہیں۔۔۔ کتنے برسوں سے میں آپ کو ڈھونڈرہی تھی۔۔۔ پلیز ہیلپ می۔۔۔ پلیز سیو می۔۔۔ ایک بار پھر۔۔۔‘‘ وہ ہاتھ جوڑکر میرے سامنے کھڑی ہوگئی۔
’’اوہ توتم اس لئے مجھ سے ملنے آئی ہو۔۔۔ شاید تم مجھے کوئی قصائی سرجن سمجھتی ہو جو۔۔۔‘‘ میں نے طنز سے بات ادھوری چھوڑدی۔’’مگر میں یہ کام نہیں کرسکتی۔ تمہیں اندازہ ہونا چاہئے تھا۔‘‘
’’ماں۔۔۔ آئی ایم سوری۔۔۔ مگر میری خوشی کے لئے۔۔۔ پلیز۔۔۔‘‘
’’یہ دیکھ رہی ہو؟۔۔۔میں نے ریت گھڑی کے ذرّے گرتے ہوئے اسے دکھائے۔۔۔ وقت ہمیشہ آگے کو جاتا ہے۔۔۔ پیچھے کو نہیں۔‘‘
سعدیہ نے’’مقیاس الساعت‘‘ کو ہاتھ میں پکڑا،چند لمحوں کے لئے اسے بغور دیکھا او رپھر الٹا کر میز پر رکھ دیا۔ شیشے کے پیمانے سے ریت کے ذرّے اب الٹی سمت میں گرنے لگے تھے۔ ہم دونوں خاموش رہیں۔ اورتمہارا وہ فلسفۂ وجودیت، تمہاری فری ول؟ پڑھ لکھ کے سب گنوادیا تم نے؟‘‘ میرا پارہ چڑھتا ہی چلا جارہا تھا۔تمہارا یہ تقاضہ انسانیت کے منافی ہے اورتم اچھی طرح جانتی ہو کہ وجودیت ،انسانیت ہے۔ او رکچھ بھی نہیں۔ بھول گئیں سارترے کادیا ہوا سبق؟‘‘
’’ماں میرا وجود صرف میرا جسم تو نہیں ہے۔ اس میں ایک دل بھی تو ہے۔۔۔ میرا دل چاہتا ہے مجھے زندگی میں محبت ہی محبت ملے میں اُس کی پھوارمیں بھیگتی ، ناچتی پھروں۔۔۔ محبت ہی میرا سامان وجود ہے۔۔۔ ورنہ میرا وجود بے کار ہے۔۔۔ ظہور کی محبت کے بغیر۔۔۔ کچھ بھی نہیں ہے۔۔۔ کچھ بھی نہیں۔۔۔ پلیز ماں۔۔۔‘‘
سعدیہ قبائلی انداز میں میرے قدموں میں جھکتی چلی گئی۔۔۔!!۔





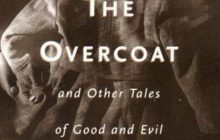



















One Comment