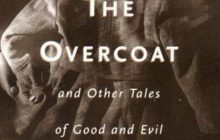خالد محمود
حال میں ہی “دی بلیک ہول اسلام آباد” نے مشہور و معروف ادبی نقاد ڈاکٹر ناصر عباس نیئر کے ساتھ ایک نشست کا اہتمام کیا۔ عام تاثر یہ ہے کہ “دی بلیک ھول” میں ہونے والی گفتگو کسی بھی شکاری، سرکاری اور من گھڑت آراء والی گفتگو سے بہتر اور بے باک ہو گی۔ مگرحسبِ دستور اور حسبِ معمول، اِس پروگرام میں گفتگو بالکل ویسے ہی تھی جیسے کسی بھی فروخت شدہ میڈیا پر نپی تلی، مصلحت اندیش اور محتاط گفتگو کی جاتی ہے۔
پوسٹ کالونیل اورہائبرڈ نظام کے تحت، زندگی سے جھوجھتے مجبور عوام پر، جو مجبوریاں لادی گئی ہیں وہ ہمارے تنخواہ دار پروفیسروں اور مراعات یافتہ دانش وروں پر اُتنی بھاری نہیں پڑتی جس قدر عوام پر پڑتی ہیں۔ مراعات یافتہ اور خوشحال آدمی کی حریت فکر اور آزادانہ رائے عام شہری سے بلند ہونی چاہئیے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ وہی انجمن ستائشَ باہمی اور وہی مصلحت اندیشی سارے ڈسکورس پر غالب تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اِس میں علمی اور اچھی باتیں شامل نہیں تھیں۔ مغربی کینن سے اچھے حوالے بھی دیے گئے مگر اپنے مقامی اصولِ تدریس پر گفتگو سے مکمل اجتناب برتا گیا تھا۔
ڈاکٹر ناصر عباس نے امریکی نقاد اور تخلیق کار سوزن سون ٹیگ کا نام تو لیا مگر جس فلسفے اور اصول تدریس میں سوزن سون ٹیگ پروان چڑھی اُس پر چند کلمات بھی نہیں کہہ سکے۔ لگے ہاتھوں اگر یہ ذکر بھی کر دیتے کہ دوسروں کے درد پر سوزن سون ٹیگ کیا کہتی ہیں تو بات “فی الحال جاری تک” آ سکتی تھی۔ تاریخ کا سبق بھی وہاں تک ہے جہاں تک تنقیدی سوچ کی دوڑ ہے۔ سوزن قاری کو یہ بتاتی ہے کہ حقیقت جس زاویے سے پیش کی گئی تھی اور جس زاویے سے اب پیش کی جا رہی ہے اُس پر سوال اٹھایا جائے۔ لیکن اِس کا کیا کیا جائے کہ بیان بازی اور مبالغہ آمیز گفتگو دھوکا دہی کے مستند اور آزمودہ اوزار ہیں۔
ہربرٹ مارکیوز نے صحیح کہا ہے کہ :کوئی بھی سیاسی نظام ایک تدریسی جاب پیدا کرنے سے پہلے، اُس کے لئے ذہن سازی بہت پہلے کر گزرتا ہے۔ اِس پر کُچھ بات کرنا واجب تھی کیونکہ آپ کلاس روم کی بجائے ایک آزاد فورم ” دی بلیک ہول” میں موجود تھے۔
علم کا جو روایتی جامد تصور ہے وہ یہی ہے: سوال پوچھنے پر زیادہ سے زیادہ اسماء گنوائے جا سکیں۔ مگر جب بیانیے اور کہانی پر کوئی موزوں سوال اٹھایا جائے تو اُسے مردود اور شیطان ڈکلیر کیا جائے۔
ناصر عباس نئیر نے ادبی کینن کی اہمیت پر زور دیا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ پہلے یہ طے کر لیں کہ کونسا ادیب چھوٹا ہے اور کونسا ادیب بڑا ادیب ہے۔ بادی النظر میں یہ لگتا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں بھی وہی فلسفہ اور اصولِ تدریش نافذ ہے جو مذہبی مدرسوں کے درسِ نظامی پر لاگو ہے۔ جیسے غزالی کو پڑھاتے چلے جانا مذہبی مقتدرہ کی مجبوری ہے مگر ابنِ رُشد اور معتزلہ کی خرد افروزی سے مذہبی اقتدار کو خطرہ لاحق ہے اس لئے اسے نصاب سے بارہ پتھر باہر رکھنا لازم ہے۔ کون ادیب چھوٹا ہے اور جھوٹا ہے یہ فیصلہ وقت اور عوام ہی کر سکتے ہیں۔
انتظار حسین کا ابہام اور بھول بھلیوں والا ادب ہندوستان کی مذہبی بنیاد پر تقسیم کے بعد، مقتدرہ کی ضرورت تھی جسے مقتدرہ اور انتظار حسین نے پوری وفاداری سے نبھایا ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ ڈومیسائل پر مبنی وفاداری کو “دی بلیک ہول میں بھی احسن طریقے سے نبھایا گیا ہے۔ لاہور ماڈل ٹاؤن جیسی اشرافیہ کی بستی میں گھر الاٹ ہونا، ریڈیو اور ادبی رسالوں سے نقد ادائیگی کروانا، انگریزی میں ترجمہ کروا کے اُسے انعام دلانے کے لئے برطانیہ روانہ کرنا؛ وفاداری بشرطِ استواری کا بہترین نمونہ ہے۔ اور جب وہاں کامن ویلتھ میں انتظار حسین کے تراجم کو درخور اعتناء نہیں سمجھا گیا تو سفارت کاری کے ذریعے فرانس کا اعزازی ایوارڈ دلایا گیا تھا۔ یار اب اور کتنا سیلی بریٹ کرتے چلے جاؤ گے؟ سرکاری تقریبات میں “گھڑی مڑی” یہ کیوں تاثر دیا جاتا ہے کہ انتظار حسین، اشفاق، بانو، ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب کے آگے پیچھے کچھ نہیں تھا۔
کیا ان کا مطابقت پرستی میں تخلیق کیا گیا ادب، آج کے بجلی کے بل میں شامل 14 ٹیکسز والے ایام میں ریلوینٹ ہے؟ کیا کہانی کا کام صرف یہی رہ گیا ہے ایک خواب آور دوا والی تاثیر پیدا کرے؟ یا کہانی وہ ہے جو قاری کے شعور کو بڑھائے اور اٰسے اتنا “اوور سائز” کرڈالے کہ قاری واپس اپنے ٖغیر فعال کلبوت میں جا کر نہ سوتا رہے؟
کسی بھی ادبی کینن میں، ہمارے یا اِن حاضر سروس پروفیسروں کی سمجھ اور تشریح کو تشکیل دینے میں، فلسفہ و اصولِ تدریس کا کردار نہایت اہم اور فیصلہ کن ہوتا ہے۔ ہمارے پڑوس میں اسے “شِکسا شاستر” کہا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ کس کے ہاتھ میں دینا ہے کہ کونسی کتاب “ادبی کینن” میں شامل ہوگی اور کون سی کتاب اِس سے باہر رکھی جائے گی؟ کیا پاکستانی یونیورسٹیز کے معلم، طلبہ کے دماغ کو خالی برتن سمجھتے ہیں جسے صرف معلم نے سیاسی مصلحت کے تحت رٹا لگواتے ہوئے بھرنا ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان میں مروجہ اصولِ تعلیم و تدریس، صرف طاقت کی حرکیات کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ کسی اختلافِ رائے یا شراکتی مکالمے پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ جامعات میں آزادیِ اظہار رائے اور آزادیِ اختلاف کے بغیر تعلیم و تدریس کے کیا معنی رہ جاتے ہیں؟ اس پر بات ہونی چاہئیے تھی۔ اس سے گریز فرمایا گیا ہے۔
سِوِکس وہ واحد مضمون تھا جو شہریوں کو اُن کے حقوق اور حکومتی بیانیے، ناقص کارکردگی پر اختلافِ رائے اور باز پُرس کے نظام کے بارے تعلیم دیتا تھا۔ اسے بتدریج نصاب سے غائب کیوں کیا گیا ہے؟
پاکستانی تعلیمات کے اصولِ اور فلسفے میں، پاؤلو فریرے کے فلسفہ تدریس، جو علم کے شراکتی مکالمے، اختلافِ رائے اور حریتِ فکر پر استوار ہے، اِس کی کوئی جگہ ہے؟ کیا تعلیم وہ ذہن سازی یا فارمیشن ہے جسے فوجی تربیت میں ایک یُونیفائیڈ کمانڈ کنٹرول کرتی ہے؟ کیا تعلیم کا مقصد ایک آزادانہ حریت فکر رکھنے والا ذمہ دار شہری پیدا کرنا نہیں ہے جو اپنے معاملات میں شراکت اور حکومتی کارکردگی پر باز پُرس کا حق بھی استعمال کرے؟
شاعروں اور ادیبوں پر مقتدرہ کا دباؤ ہمیشہ رہا ہے۔ انٹر نیٹ اور سوشل میڈیا سے بہت پہلے انتہائی نامساعد حالات میں بھی بات کرنے والے نان کنفارمسٹ بات کر گئے اور قید و بند کی صعوبتیں بھی جھیل گئے۔
کسی بھی تہذیب کا زوال اُس تہذیب کے چرواہوں، راھک، واھک اور مزدور کسان کی محنت کا زوال نہیں ہوتا۔ یہ ہمیشہ پڑھے لکھے، ولایت سے اسناد یافتہ مدرسین اور بیورو کریٹس اور طاقتوروں کا اخلاقی زوال ہوتا ہے۔ پیسہ نیچے سے جبراً بٹور کر اوپر بھیجا جاتا ہے اور جس قسم کے بھی تدریسی اصول کو لاگو کیا جاتا ہے، وہ آپ حضرات سے بہتر کون جانتا ہے؟
ہمارے دور کے ہر شعبے کا زوال پڑھے لکھے مراعات یافتہ حکمران اشرافیہ کا زوال ہے۔ 15 کروڑ کی عددی اکثریت کے باوجود، پنجاب پیٹروگراڈ کیوں نہیں بنتا؟ اِس پر آپ کی تنقیدی تھیوری کیا کہتی ہے؟ مانا ہمیں انقلاب کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ مگر یہاں تو “انا ہزارے” جیسی غیر فعال علامتی مزاحمت بھی نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لئے کہ جیسے آپ کو پڑھایا گیا تھا، آپ بھی ویسے ہی آگے پڑھائے جا رہے ہیں۔
♠