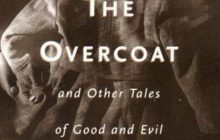“تم مر رہے ہو، الیوشا؟ “ تانیہ کا لہجہ سوالیہ تھا۔
“ ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتے۔” الیوشا نے فطری صاف گوئی سے جواب دیا۔ ایک دن مرنا بھی ہوتا ہے۔
“ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولا “ ۔۔۔۔ اور دیکھا !یہ بھی اچھا ہی ہوا۔
انھوں نے ہمیں شادی نہیں کرنے دی۔ اب کتنا افسوس ہوتا۔ وہ دھیرے دھیرے پادری کے کہے الفاظ دہراتا رہا۔
اسے خیال آ رہا تھاکہ اگر آدمی سب کی بات سنتا رہے اور کسی کو ناراض نہ کرے تو نہایت اطمینان سے زندگی گزار سکتا ہے۔
◊
یہ ٹالسٹائی کی ایک کہانی کا آخری حصّہ ہے جس میں محرومیوں کی زندگی گزارنے والا ایک لڑکا مر رہا ہے۔ وہ کسی امیر کے گھر میں کام کرتا ہے اور وہاں ایک لڑکی کو پسند کرنے لگتا ہے۔ اس نے محتاجی کی زندگی میں صبر شکر سے زندہ رہنا ہی سیکھا ہے۔ جب اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ مر رہا ہے تو وہ اسے بھی صبر شکر والی بات سمجھ کر ایسے قبول کر لیتا ہے کہ جیسے یہ کوئی معمول کا کوئی کام ہو۔
یہ بات درست بھی ہے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتے، ہمیں ایک دن مرنا بھی ہوتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو فطرت کے اپنے آپ کو جاری رکھنے کے لیے بنیادکا درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح جیسے زمین کی زرخیزی کے اجزا کو واپس اپنے اندر سمونے کے لیے نامیاتی اشیا گل سڑ (Decompose) کر دوبارہ اپنے آپ کو زمین کا جزو بنا لیتی ہیں۔ ہم انسان بھی پودوں اور دیگر جانداروں کی طرح اسی فطرت کا حصہ ہیں جس میں جانداروں کی موت ایک نئی زندگی کی وجہ بنتی ہے۔
یہ تو فطرت کی بات ہے اور انسان دیگر جانداروں کے برعکس اپنی ذہنی صلاحیّتوں کے باعث ایسی دنیا بسانے کی اہلیت رکھتا ہے جو ضروری نہیں کہ فطرت سے تال میل رکھتی ہو۔ اسی ذہنی استطاعت کے باعث ہمیں ایک ایسی خود اعتمادی اور اپنے آپ پر فخر کرنے کی توفیق ملی ہے کہ جس کے بھروسے ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو تبدیل کرکے فطرت کو اس کی انتہائی حدود تک لے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ سب ہم انسان کرتے ہیں اس لیے ہم اپنے آپ کو بھی اسی احساسِ فتح کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے اپنے جسم کو اس حد تک سمجھ لیا ہے کہ ہمیں فطرت کا پیدائش اور موت کا کھیل اپنی دسترس میں قید نظر آتا ہے۔ یہ احساس صرف سائنسدانوں اور محققین میں ہی نہیں، عام لوگ بھی اس اجتماعی احساسِ برتری کو محسوس کرتے ہیں اور انھیں اپنے آپ پر غرور سا ہونے لگتا ہے۔
اسی مادی ترقی اور اس سے پیدا ہونے والے فکری پس منظر میں لوگ اپنے مرنے کو ناقابلِ یقین عندیہ مانتے ہیں۔ حالانکہ اس مادی ترقی اور اس سے پیدا ہونے والے غرور کی مستحق انسانی برادری بحیثیت مجموعی بنتی ہے کیونکہ انسان ایک فرد کے طور پر تو مر جاتا ہے مگر انسانوں کا ورثہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتا رہتا ہے ۔اس طرح انسانی ترقی کا سلسلہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل تک پہنچتے پہنچتے مزید حیران کن منزلیں طے کر لیتا ہے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک فرد تو مر جاتا ہے مگر انسان زندہ رہتا ہے۔ یہی وہ ابہام ہے جو کسی بھی فرد کی انفرادی زندگی کی غیر پائیداری کو اجتماعی انسانی تسلسل کی پائیداری سے الجھا دیتا ہے۔ اسی الجھائو کے باعث ہم نے سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ اس دنیا میں مستقل طور پر رہنے کے لیے آئے ہیںاور اپنی زندگی کوطول دینے لیے ایڑھیاںرگڑتے ہیں۔
بولیوڈ کی ایک فلم 102 Not Out اسی احساس پر تبصرہ کرتی ہے۔ اس فلم کا مرکزی کردار ایک بوڑھا ہے جو ایک سو دو سال کا ہے مگر وہ اپنی زندگی کو فطرت کے ایک تحفے کے طور پر مانتا ہے اور اسے اس کے ساتھ چمٹنے کی کوئی آرزو نہیں۔ شاید اسی وجہ سے وہ ایسی طویل عمر تک پہنچ پایا۔ دوسری جانب اس کا بیٹا اپنی زندگی کو طوالت دینے کے لیے زندگی سے الجھ رہا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو طول دینے کے لیے کچھ عملی اور کچھ خوشنما خواہشات کی بیساکھیوں کے سپرد کر چکا ہے۔
مثال کے طور پر وہ روزانہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اپنی صحت کی عافیت سننے کے بعد واپس آجاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو مخصوص بند شوں میں باندھ چکا ہے۔ مثلاً یہ کہ وہ اپنی ایک پرانی چادر کے بغیر سو نہیں سکتا۔ ایک بات جو اس کے خیال میں اس کے آنے والے بڑھاپے کے بے بسی کے ایام میں اس کے کام آئے گا وہ یہ ہے کہ اس کا بیٹا جو امریکہ میں رہتا ہے وہ اس کا خیال رکھے گا۔ یہ وہ لڑکا ہے جو اپنے آپ کو مکمل طور پر مشینی اور جانوروں جیسی خود غرضی کو سونپ چکا ہے۔
واضح رہے کہ مشین اور جانوروں میں دوسروں کے ساتھ ہمدردی کی صلاحیت نہیںہوتی ۔مشین صرف وہی کر سکتی ہے جس کام کے لیے اسے بنایا گیا ہو۔ جانور صرف وہی کر سکتے ہیں جیسی تقویم فطرت نے جبلت کی صورت انھیں سونپی ہو۔ان دونوں میں دوسروں کا احساس کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ جن بچوں کی بچپن سے بڑوں کی اسی غرض مندی کے تحت پرورش ہو وہ ایسے مشینی اور بے حس جانور ہی رہ جاتے ہے۔
یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جب ایک ماں بچے کو پیار کرتے ہوئے اسے اپنے پیار کا اسیر بنانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ دراصل بچے سے پیار نہیں کر رہی ہوتی بلکہ وہ چاہتی ہے کہ بچے اس سے پیار کریں ۔ وہ دراصل ایسا پیار کا ڈھونگ رچا کراپنے اندر پیار کی محرومی کو ختم کرنے کی سعی کرتی ہے۔ اسی طرح جب والدین بچوں کی اس طرح پرورش کرتے ہیں کہ وہ کل کو ان کا سہارا بنیں گے تو دراصل وہ بچوں کو خاموشی سے یہ بات سمجھا دیتے ہیں کہ وہ ان کے محتاج ہیں اور بچے اپنے آپ کو ایک حاکمانہ درجے پر براجمان محسوس کرنے لگتے ہیں۔
یہی صورتحا ل اس فلم میں بھی پیدا ہو تی ہے۔ اس شخص کے بیٹے کے پاس ان کے لیے کو ئی وقت نہیں بلکہ مختلف حوالوں سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے باپ او ر اہل ِ خانہ کو کوئی وقعت نہیں دیتا۔ واضح رہے کہ جب اس کی ماں الزائمر کی مرض سے مر رہی ہوتی ہے تو وہ سب کو بھول جاتی ہے البتہ اپنے بیٹے کو نام یاد رکھتی ہے۔ یہ جذباتی عنصر ہے ۔تاہم اس کا بیٹا اس لیے آنے سے معذرت کر لیتا ہے کہ چھٹی لینے کے لیے لمبا نوٹس دینا لازم ہوتا ہے۔ وہ ایسی بے رخی کی حرکات کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ I hope you understand ۔
اسی طرح جب اس کا دادا اسے جائیداد کی تقسیم کے لیے کہتا ہے تو وہ اپنا پروگرام تبدیل کرکے فوراًآنے کا بندوبست کر لیتا ہے۔ فلم میں اس کے والد نے ان تمام دقتوں کے باعث اپنی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے۔ اس کا باپ اسے اس ناقابلِ زیست زندگی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ ان تمام بودے بھلیکھوں سے نجات دلانے میں مدد کرتا ہے ۔
اس وقت ہمارے معاشروں میں ایک بنیادی تبدیلی آ رہی ہے ۔ روایتی طرز ِ زندگی ختم ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ روایتی رشتوں کے بندھن اور توقعات بھی ختم ہو رہی ہیں۔ ایسے میں ضروری ہے کہ اس نئی صورتحال کو کسی جذباتیت سے الگ اس کے حقیقی تناظر میں سمجھا جائے ۔ یہ فلم اس لحاظ سے اہم ہے کیونکہ اس میں ان حالات کا بڑے سادہ مگر موثر انداز میں احاطہ کیا گیا ہے۔
یہ بڑی عمر کے لوگوں کو مشورہ دیتی ہے کہ وہ دوسروںاپنی اولادوں پر غیر حقیقی اور جذباتی توقعات رکھنے کی بجائے اپنے آپ پر بھروسہ کریں اور موت کو ایک حقیقت سمجھ کر اسے قبول کر لیں۔ اسی طرح جیسے زندگی ایک سچائی ہے اسی طر ح موت بھی ایک سچائی ہے ۔ آپ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے، ایک دن آپ کو یہاں سے جانا ہو گا۔ البتہ جس نسل سے آپ کا تعلق ہے وہ نسل آپ کے وسیلے سے زندہ رہتی ہے۔
♦