اجمل کمال
افسانوں کو پرچۂ ترکیبِ استعمال کے ساتھ شائع کرنا اردو کے ادبی رسالوں کے مدیروں کا تازہ ترین شعف ہے۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ اس کی بدولت بہت سے پڑھے لکھے لوگ افسانے پڑھنے کی زحمت سے بچ جاتے ہیں۔ پاکستان کے ایک معروف نقاد کے چھوٹے بھائی شمیم احمد نے اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر ‘‘سوغات’’، بنگلور، (شمارہ ۲) کے خطوں کے کالم میں باقاعدہ اپنے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ افسانے وغیرہ تو ایڈیٹر لوگ رسالے کی بِکری بڑھانے کی چاٹ میں چھاپتے ہیں۔ ان کے نزدیک ادبی رسالوں میں صرف تجزیے اور مقالے شائع ہونے چاہییں۔ یہ بات بڑی حد تک درست ہے۔ افسانے وغیرہ تو ثانوی اہمیت کی تحریریں ہیں جن سے نقادوں کو اپنے وقیع تنقیدی مقالوں کے لیے نت نئے مضامین سوجھتے ہیں۔ ظاہر ہے ان مقالوں یا تجزیوں کے لکھے جانے کے بعد افسانوں کا کیا مصرف رہ جاتا ہے، انھیں تلف کردینا چاہیے۔ مگر مذکورہ برادر خورد کی بات سے پورا اتفاق کرنا ذرا دشوار ہے۔ افسانوں کو بھی اگر تجزیوں کے قدموں میں جگہ مل جائے تو یہ بات درحقیقت فائدے سے خالی نہیں۔ کیا عجب کسی افسانے کا کوئی ٹکڑا تجزیے میں پیش کیے گئے کسی نادر نکتے کی گہرائی کو سمجھنے میں کام آجائے۔ اس لیے غوغاے برادراں خواہ کچھ بھی ہو، میں تو ترکیبِ استعمال کے ساتھ ساتھ افسانہ بھی چھپا ہوا دیکھنے کے حق میں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ‘‘فسادات کے افسانے: تجزیوں کے ساتھ’’ قسم کے عنوانات پڑھ کر میرا دل باغ باغ ہوجاتا ہے۔
اس موجودہ رجحان سے جدید اردو ادب میں نقادوں کی بڑھی ہوئی وقعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ دن لد گئے جب سعادت حسن منٹو یہ کہہ کر نقادوں کا مضحکہ اڑایا کرتے تھے کہ اردو ادب کا بھلا اس میں ہے کہ جو کچھ نقاد کہیں اُس کا اُلٹ کیا جائے۔ آج کل تو اردو کے افسانہ نگاروں کو نقادوں سے یہ نیازمندانہ شکوہ کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ آپ ہمارا خاطرخواہ ذکر ہی نہیں کرتے۔ ہم کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو۔ ظاہر ہے انھیں یقین ہو چلا ہے کہ پڑھنے والوں سے ان کا رابطہ صرف نقادوں کے واسطے سے ممکن ہے۔ جب تک کسی جغادری نقاد کا کرم نہ ہو، افسانہ نگار کی بات نہیں بن سکتی۔
سابق یوگو سلاویا کا ایک بانکا ناول نگار میلوراد پاویچ اپنے انوکھی طرز کے ناول
Dictionary of the Khazars
کے تمام تر ابتدائیے میں پڑھنے والے سے خطاب کرنے کے بعد آخری پیراگراف میں لکھنے والے سے یوں گویا ہوتا ہے:۔
As for you, the writer, never forget the following: the reader is like a circus horse which has to be laught that it will be rewarded with a lump of sugar every time it acquits itself well. if that sugar is withheld, it will not perform.
(اور) اے لکھنے والے ! ایک بات ہمیشہ کے لیے گرہ میں باندھ لے: پڑھنے والا سرکس کے گھوڑے کی مثال ہے جس کو یہ سکھلانا ضروری ہے کہ ہر بار اچھا کام کرنے پر اسے گڑ کی بھیلی ملے گی۔ یاد رکھ، اگر اسے گڑ کی بھیلی نہ ملی تو وہ کرتب نہیں دکھائے گا۔
پاویچ کا آخری فقرہ نقادوں کے بارے میں ہے:۔
As for essayists and critics, they are like cuckolded husbands; always the last to find out.
رہے مقالہ نگار اور نقاد، تو وہ فریب خوردہ خاوندوں کی طرح ہیں، انھیں سب سے آخر میں پتا چلتا ہے۔
منٹو کے علاوہ محمد حسن عسکری کی یہ بات بھی لوگوں کے ذہن سے محو سی ہو گئی ہے:۔
“اول تو ادب میں تنقید کی حیثیت کائی یا پھپھوندی کی سی ہے، بجائے خود اس کی کوئی ہستی نہیں، لیکن اگر یہ اپنی ثانوی حیثیت پر قانع رہے۔ تو ادب کے لیے مفید بھی ہو سکتی ہے، بلکہ آپ چاہیں تو ضروری بھی کہہ لیجیے۔ مگر تنقید ضروری یا فائدہ مند صرف اُسی وقت تک ہو سکتی ہے جب تک خادمہ کے فرائض انجام دینے پر قانع رہے۔ تنقید کا حوصلہ اس سے آگے بڑھا اور تخلیقی ادب کا ستیاناس ہوا“۔
اردو تنقید کے تازہ خداؤں کا تصور کرکے یہ اقتباس نقل کریں تو ہر علامتِ وقف کی جگہ قوسین میں معاذاللہ لکھنا پڑے گا، کیونکہ لکھنے والوں میں گستاخی کی وہ رسم متروک ہو چکی ہے جو اقبال کے زمانے میں رائج تھی اور انھوں نے اپنے ‘‘فرشتہ صید و پیمبرشکار و یزداں گیر’’ والے پیرِ رومی سے سیکھی تھی۔ وہ ہوتے تو شاید پوچھتے:
بہ جہانِ دردمنداں تو بگو چہ کار داری؟
تب وتابِ ما شناسی؟ دلِ بےقرار داری؟
اِدھر تو حال یہ ہے کہ نقادوں نے ‘‘لکھت لکھتی ہے لکھاڑی نہیں’’کا نعرہ لگا کر بیچارے لکھنے والے ہی کو دیس نکالا دے دیا ہے۔ غنیمت ہے کہ ابھی ساختیات کے میدان میں اولیت کے جھگڑے نے ان سب کو مشغول کر رکھا ہے۔ اگر کبھی وہ اس سے فارغ ہوے تو انھیں معلوم ہو گا کہ اس تماشے سے بیزار ہو کر پڑھنے ولا بھی کب کا رخصت ہو چکا ہے۔ لیکن عسکری کا مندرجہ بالا اقتباس اولیت کا ایک اور جھگڑا کھڑا کر دیتا ہے جو انڈے اور مرغی کے قضیے کی قبیل سے ہے، یعنی یہ کہ نقادوں نے خدائی کا دعویٰ پہلے کیا یا اردو ادب کا ستیاناس پہلے ہوا۔ اس کا سراغ عسکری کے افسانوں کے پہلے مجموعے ‘‘جزیرے’’ کے اختتامیے (محررہ ۳ فروری ۱۹۴۳ء) میں ان کے اس اعلان سے مل سکتا ہے کہ اب اردو ادب کو تخلیق سے زیادہ تنقید کی ضرورت ہے۔
اب یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ اگر ہماری تنقید خادمہ کے فرائض انجام دینے پر قانع رہتی تو اردو ادب کی شکل آج کیا ہوتی۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ لکھنے والے اُس صورت میں نقادوں سے کیا توقعات باندھتے یا کون سے مطالبات کرتے۔ کیا عجب کہ وہ ان سے کوئی سروکار رکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرتے۔ منٹو کو بھی تحقیر کے مظاہرے کی ضرورت نہ پڑتی اگر اردو کے نقادوں نے
Right Man’s Burden
سمجھ کر ہدایت نامۂ خاوند جاری کرنے کا غیرضروری بوجھ اپنے ناتواں کاندھوں پر نہ اٹھا لیا ہوتا۔ لطف یہ ہے کہ ان نقادوں میں سے بعض ایسے بھی تھے جو خاوند بنے بغیر براہ راست ہی خداوند کے درجے پر جا پہنچے۔ تخلیقی فنکاروں کے لیے بڑی آسانی ہے۔ تعلّی کی دودھاری تلوار خودبخود تصفیہ کر دیتی ہے۔ پڑھنے والے یا تو ان کی کج ادائی کو ہنسی خوشی یا جبراًقہراً برداشت کرجاتے ہیں یا لطیفہ سمجھ کر محظوظ ہو لیتے ہیں۔
عسکری کی بات اس نکتے کو بخوبی واضح کر دیتی ہے کہ ادب کے بارے میں لکھی جانے والی یہ تحریریں تخلیقی ادب بہرحال نہیں ہیں۔ یہ اَور بات ہے کہ آج کل ادبی رسالے اپنے بیشتر صفحات ان کی نذر کر دیتے ہیں، غالباً یہ سوچ کر کہ جہاں ستیاناس وہاں سواستیاناس سہی۔ دوسرا نکتہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ انکسار تخلیقی ادیب کے لیے ضروری ہو یا نہ ہو، نقاد کے لیے لازمی ہے۔
ادیب اور پڑھنے والے کا رشتہ سیدھاسادا باہمی ضرورت کا ہے۔ ادیب کیوں لکھتا ہے، یہ اس کا درد سر ہے۔ پڑھنے والا تو ادب پڑھنے کی زحمت گڑ کی بھیلی پانے کے لالچ میں اٹھاتا ہے، اور اس گڑ کی بھیلی کی معنویت ہر شخص کے لیے مختلف ہو سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان دونوں کے آزادانہ لین دین میں نقاد کب، کہاں سے اور کیوں داخل ہوا۔ کب کا تعین کرنا آسان ہے۔ نقاد کی ولادت زمانی اعتبار سے ادیب اور پڑھنے والے کے بعد ہوتی ہے۔ نقاد کہاں سے آتا ہے، اس کا ایک ممکنہ جواب عسکری نے یوں دیا ہے:۔
“آدمی نے کوئی کتاب پڑھی، اچھی معلوم ہوئی، جی چاہا اوروں کو بھی بتاؤں۔ اب اس نے ایسے تصورات اور اصطلاحیں ڈھونڈیں جن کی مدد سے وہ دوسروں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ہوئی تنقید۔ اب اس میں کلیاں پھندنے جتنے جی چاہے ٹانک لیجیے“۔
یعنی تنقید کی حیثیت دو پڑھنے والوں کے درمیان ادب کی تحسین کے سلسلے میں مکالمے کی ٹھہری۔ نقاد، جو گویا ایک ترقی یافتہ قاری ہے، دوسروں کو کسی ادب پارے کے بارے میں اپنے نقطۂ نظر کا قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بات اسے تخلیقی ادیب سے کئی معنوں میں ممتاز کر دیتی ہے۔ اسے وہ تمام آزادیاں حاصل نہیں ہوتیں جو تخلیقی ادیب کی جاگیر ہیں۔ وہ اپنی بات دلائل اور شہادتوں کے ساتھ کہنے کا پابند ہے۔ اس کے لیے اپنے نقطۂ نظر کی معقول وضاحت بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ فی بطنِ شاعر کے وزن پر فی بطنِ ناقد کی رعایت کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ معروضیت کے بغیر وہ اپنا کام ٹھیک طرح انجام نہیں دے سکتا۔
بعض تخلیقی ادیبوں نے بھی تنقید لکھی ہے۔ پڑھنے والے کے لیے تنقید کی اِس قسم میں معنویت کا ایک پہلو اَور بھی ہے۔ اس سے ادیب کی افتادِ طبع اور ادبی معیاروں کا سراغ ملتا ہے جو اس کی تخلیقی تحریروں کی تحسین میں بھی مددگار ہو سکتے ہیں۔ کچھ ادیب ایسے بھی تخلیقی تحریروں کی تحسین میں بھی مددگار ہو سکتے ہیں۔ کچھ ادیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس گڑ کی بھیلیاں نہیں رہتیں اور وہ ادب تخلیق کرنا چھوڑ کر نقاد بن جاتے ہیں۔ عسکری نے ایسے لوگوں کو“ادب کے سر کی جوئیں” قرار دیا ہے۔ اسے بھی انکسار ہی کی ایک قسم سمجھیے۔ عسکری کا شمار بھی ان منکسرمزاج لوگوں میں کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ادیبوں پر کبھی کبھی“قحبہ چوں پیر شود” کی پھبتی بھی کسی جاتی ہے، مگر یہ عسکری پر ٹھیک نہیں بیٹھتی کیونکہ وہ تو جوانی ہی میں تخلیق سے نائب ہو گئے تھے، اور جوانی کی توبہ کا مقام تو آپ جانتے ہی ہیں کتنا بلند ہوتا ہے۔
ادیب اور پڑھنے والے کا رشتہ ان دونوں کی انفرادی آزادی سے مشروط ہے۔ لکھنے کی آزادی اور پڑھنے کی آزادی ایک دوسرے کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتیں۔ یوں تو ادب تنہائی کا مشغلہ ہے: لکھنے والا اسے اپنے کمرے میں بیٹھ کر لکھتا ہے اور پڑھنے والا اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھتا ہے۔ مگر دنیا میں ان دونوں کے علاوہ بھی بہت کچھ موجود ہے۔ آپ چاہیں تو اسے مختصراً ظالم سماج بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس مخلوق کے لیے تنقید ایک الگ ہی معنویت رکھتی ہے۔ عسکری کے لفظوں میں:۔
“تخلیق میں شعور کا دخل تو ضرور ہوتا ہے، لیکن لاشعوری عوامل تخلیق پر اس بُری طرح حاوی رہتے ہیں کہ لکھنے والے کو خود پتا نہیں چلتا کہ میری کوشش کے آخری نتائج کیا ہوں گے۔ اسی لیے تخلیقی کام کرنے والوں سے حکمران ذہنیت کے لوگ ہمیشہ خائف رہے ہیں۔ البتہ ادب میں تنقید ایسی چیز ہے جس کی راہیں متعین کی جا سکتی ہیں۔ لہٰذا حکمران ذہنیت تنقید کو زیادہ قابلِ اعتبار سمجھتی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اور پچھلے تیس سال سے تو تنقید ادیبوں اور پڑھنے والوں پر پہرہ دے ہی رہی ہے۔ تنقید سے ذہنوں کو ‘ڈھالنے’کا کام لیا جا رہا ہے“۔
حکمران ذہنیت اگر تخلیقی ادیب سے خائف رہتی ہے تو اسے ادیب اور پڑھنے والے کے سیدھے سادے رشتے سے ضرور کچھ نہ کچھ خطرہ محسوس ہوتا ہو گا۔ اس خطرے کی تفصیل یہاں غیرضروری ہے لیکن اتنا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ادیبوں اور حکمران ذہنیت رکھنے والوں کے مقاصد میں ٹکراؤ کا امکان موجود رہتا ہے۔ خطرے کو زائل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ادیب اور پڑھنے والے کے رشتے میں دخل دیا جائے، یعنی لکھنے اور پڑھنے کی آزادی کو محدود کیا جائے۔ کتابوں کو قابلِ ضبطی سمجھنا، انھیں جلانا، ان کی اشاعت اور فروخت پر پابندی لگانا (یا لگوانا) اور ادیبوں کے خلاف واجب القتل ہونے کے فتوے جاری کرنا، ان سب کو تنقید کی انتہائی بگڑی ہوئی شکلیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثالیں اردو ادب کی تاریخ میں بھی مل جاتی ہیں: ‘‘سوزِ وطن’’ (پریم چند)، ‘‘انگارے’’، یگانہ، منٹو وغیرہ۔ لیکن اس کھلی جارحیت سے ہٹ کر تنقید کی ایک اور قسم بھی ہے جس کی طرف عسکری نے اشارہ کیا، یعنی ادیب اور پڑھنے والوں پر پہرہ دینا اور ذہنوں کو ڈھالنا۔ یہ تمام صورتیں اس وقت سامنے آتی ہیں جب تنقید کا حوصلہ اس کی حیثیت سے بڑھ جاتا ہے اور وہ اس انکسار سے محروم ہو جاتی ہے جو اس کے وجود کی لازمی شرط ہے۔
جہاں تک ادیب کو رشدوہدایت دینے کا تعلق ہے، یہ تنقید کا اپنے منصب سے تجاوز ہے لیکن نقاد کی ایک حیثیت پڑھنے والے کی بھی تو ہے، اور لین دین کے رشتے سے پڑھنے والے کو ادیب سے کچھ نہ کچھ مطالبات کرنے کا بھی حق ہے۔ تاہم، انکسارے سے فراغت پا کر نقاد اس اہم بات کو فراموش کردیتا ہے کہ پڑھنے والا اپنے مطالبات ہدایات کی صورت میں نہیں بلکہ پسند ناپسند کی شکل میں ادیب تک پہنچاتا ہے۔ کوئی ادیب کسی مخصوص مطالبے کو ماننے یا نہ ماننے کا پابند نہیں کیونکہ وہ اپنا کام ناکامی کا پورا خطرہ مول لے کر کرتا ہے۔ پڑھنے والے کو اگر اس کی تخلیق کامیاب محسوس نہ ہو تو وہ اسے رد کر سکتا ہے۔
یہ بھی ضروری نہیں کہ ادیب کے پیش نظر اس کے ہم عصر، ہم وطن یا ہم قبیلہ پڑھنے والے ہی ہوں۔ پڑھنے والا بھی آزاد ہے کہ اگر اسے گڑ کی بھیلی ایک ادیب سے دستیاب نہیں ہوتی تو کسی اور ادیب کا انتخاب کر لے۔ اپنی زبان کا ادیب نہ سہی کسی اور زبان کا سہی۔ اِدھر یہ بات نقاد کے ذہن سے اتری، اُدھر اس نے حکمران ذہنیت اختیار کی۔ اہلِ قلم کی سرکاری کانفرنسیں اور پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے قوانین ہوں یا ہدایت ناموں جیسے مضامین، ادیب کو ڈنڈے کے زور سے یا انگلی پکڑ کر اپنے راستے پر چلانے کا شوق اپنا رنگ دکھائے بغیر نہیں رہتا۔ اب یہ ادیب پر منحصر ہے کہ اس سے کس طرح نمٹتا ہے، منٹو کی طرح ہوش مندی سے یا یزدانی ملک کی طرح تابعداری سے۔ (آپ پوچھیں گے یہ کون صاحب ہیں؛ میرا بھی عسکری صاحب سے یہی سوال ہے)۔
پڑھنے والے کے لیے تنقید کی جارحانہ شکلوں ۔۔ مثلاً کتاب سوزی، قانون سازی، مقدمے بازی، فتویٰ پردازی وغیرہ ۔۔ کو پہچاننا آسان ہے، لیکن یہ طے کرنا اتنا آسان نہیں کہ کب نقاد نے اس کو قائل کرنے کے بجاے اس پر پہرہ دینے اور اس کے ذہن کو اپنے مطلوبہ سانچے میں ڈھالنے کا کام شروع کردیا۔ ایک حد تک اس کا فیصلہ پڑھتے ہوئے یہ احتیاط ملحوظ رکھ کر کیا جا سکتا ہے کہ نقاد نے کوئی دعویٰ بغیر دلیل یا شہادت کے تو نہیں کیا یا وہ کسی شہادت کو مسخ کر کے تو پیش نہیں کر رہا۔ لیکن زندگی پیچیدگیوں سے اتنی خالی ہوتی تو کہنا ہی کیا تھا۔ نقاد ادیب نہ سہی، اپنی بات کہتا تو لفظوں ہی میں ہے۔ لفظوں کے استعمال کی ذرا مشق ہوجائے تو دلیل کی عدم موجودگی پر پردہ ڈالنے اور شہادت کی شکل تبدیل کرنے کی مہارت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔
بڑے ادیبوں کی تحریریں ہمیں اس امر کا متواتر احساس دلاتی ہیں کہ زندگی بہت پیچیدہ ہے۔ زندہ افراد کے طور پر ادیب، قاری اور نقاد، تینوں اپنے اپنے دائروں میں اس پیچیدگی سے نبردآزما ہوتے ہیں، اپنے اپنے ذہن میں اس پیچیدہ دنیا کا نقشہ تیار کرنے میں مصروف رہتے ہیں، اور اس پیچیدگی کا خاصّہ ہے کہ حتمی طور پر کسی کی گرفت میں نہیں آتی۔ ادیب اپنے بنائے ہوے نقشے کو ادبی تخلیق کی صورت میں سامنے لاتا ہے۔ نقاد کا کام ادبی تخلیق کو زندگی کی پیچیدگی کے سامنے رکھ کر ان دونوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرنا ہے لیکن اس کی تحریر کی نوعیت ادیب کی تخلیق سے جدا ہوتی ہے کیونکہ اس میں سے وہ عنصر غائب ہوتا ہے جسے ‘‘چیزے دیگر’’ کہا گیا ہے۔ رہا پڑھنے والا، تو اس کے سامنے یہ دونوں نقشے تحریر کی شکل میں آتے اور زندگی اور ادب کے بارے میں اس کے شعور پر اثرانداز ہوتے ہیں۔ اس کے شعور کا نقشہ بھی مسلسل تغیرپذیر رہتا ہے۔
تنقید کی خدائی پڑھنے والے کے ذہن کو اپنے مطلب کا بنانے کی اسی گنجائش سے شروع ہوتی ہے۔ جس چیز کو عسکری نے حکمران ذہنیت کہا ہے وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے تنقید کے اوزاروں کو بھی اپنے ہتھیاروں میں شامل کر لیتی ہے۔ پھر نقاد دھونس، دھاندلی اور بددیانتی سے کام لینے لگتے ہیں، بقولِ عسکری“بڑے سے بڑے ادب کی ایسی تشریح کرتے ہیں کہ شکل پہچاننے میں نہیں آتی“، ادب کو اپنی مرضی کے خانوں میں بانٹا جانے لگتا ہے، شہادتیں مسخ کی جانے لگتی ہیں، فتوے جاری ہونے لگتے ہیں، دلیل کی جگہ پینترے بازی لے لیتی ہے، اور جہاں اس یپنترے بازی سے کام نکلتا دکھائی نہ دے وہاں صاف صاف لکھنے اور پڑھنے کی آزادی کو محدود کرنے کا مطالبہ ہونے لگتا ہے۔ یہ دعویٰ کہیں کنایتاً کیا جاتا ہے اور کہیں صاف الفاظ میں۔ دیکھا گیا ہے کہ آدمی کیسا ہی بے ہودہ اور بے بنیاد دعویٰ کیوں نہ کرے، کچھ نہ کچھ ماننے والے پیچھے لگ ہی جاتے ہیں۔
خدامِ ادب کو خدایانِ ادب کا درجہ مل جانے کے بعد یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انھیں فانی انسانوں یعنی تخلیقی ادیبوں پر فوقیت دی جائے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ فسادات کے موضوع پر شائع شدہ تحریروں کے انتخاب کی ابتدا ایک نہیں دو تنقیدی مضامین سے ہوتی ہے۔ بلکہ یہ پھپھوندی یا کائی آئینے کے دونوں رخوں پر لگی ہوئی ہے، یعنی اس کا اختتام بھی ایک تجزیے پر ہوتا ہے۔ ان تینوں میں مضمون تو واحد ہی ہے، یعنی عسکری کا“فسادات اور ہمارا ادب“، باقی دونوں یعنی ممتاز شیریں اور آصف فرخی کی معروضات تو اسی کی شرحیں ہیں، بلکہ آپ چاہیں تو مصرع اٹھانے کی کوششیں کہہ لیجیے۔
فسادات کا ادب’’ کی اصطلاح کو بھی نقاد کے ذوقِ خدائی کا معجزہ سمجھنا چاہیے“۔ بہ قولِ عسکری:۔
“ایک لحاظ سے نقاد بھی ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ ان بیچاروں کو فنکار کے تخلیقی کرب کا تجربہ ہی کیا ہے۔ ان کے نزدیک تو ادب‘موضوعات‘ کے متعلق ہوتا ہے، یعنی جس طرح اسکول کے لڑکے کے سامنے امتحان کا پرچہ آ گیا اور اس نے جواب لکھ دیے، نقادوں کے خیال میں تخلیقی عمل بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ لکھنے والے کے سامنے حیات و کائنات سے متعلق چند مسائل پیدا ہوئے اور اس نے اپنی رائے بیان کر دی“۔
کم از کم پاکستان میں رفتہ رفتہ عسکری کو ایسے مقام پر فائز کر دیا گیا ہے جو غالباً رحمت اللہ علیہ کی کھونٹی سے بھی کچھ اوپر واقع ہے۔ اپنے لیے نت نئے مسجود تراشنا انسانوں کا ایک دلچسپ مشغلہ رہا ہے اور یہ معصوم سرگرمی ہر قسم کے اعتراض سے ماورا ہے۔ اس شغلِ بےکاری میں سرگرم برادرانِ خورد نے عسکری کو پورا حق دے دیا ہے کہ ادب، سیاست، فلسفہ، الٰہیات، نفسیات، جس موضوع کو جیسے چاہیں اوڑھیں یا بچھائیں، اور اپنا فرض یہ ٹھہرا لیا ہے کہ ان کے بستربند کے ساتھ لپٹتے اور کھلتے رہیں۔
اس میں بھی کوئی خاص حرج نہیں؛ مگر مشکل تب پڑتی ہے جب ان حضرات کی سمجھ میں یہ چھوٹی سی بات نہیں آتی کہ جو شخص عسکری کی تحریروں کو وحیِ الٰہی سے مختلف چیز سمجھتا ہو اُس پر ان برخوردارانِ بستر کی پیروی لازم نہیں آتی۔ حال یہ ہے کہ یہ لوگ عسکری کے بقول ‘‘بمچو ما ڈنگرے نیست’’ کی تفسیر بنے رہتے ہیں۔ اِدھر کسی نے منھ کھولا کہ عسکری کے پاؤں گیلی مٹی کے ہیں، اُدھر برادرانِ خورد نے اس کی ٹانگ لی۔ سرحد کے اُس طرف کا حال نہیں معلوم، ادھر کے لوگ تو عسکری راج میں زندہ رہنے کے اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ چیرہ دستوں کی چیرپھاڑ سے بچنے کے لیے چپ رہنے ہی میں عافیت سمجھنے لگے ہیں۔
چونکہ اردو تنقید کے معبدِ سیزدہ خدایاں میں عسکری کا درجہ خاصا بلند ہے، اس لیے ‘‘فسادات کے ادب’’ کا جو بھی انتخاب شائع ہوتا ہے اس میں عسکری کا زیرِ بحث مضمون ضرور شامل کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ممتاز شیریں کی ادارت میں نکلنے والے رسالے“نیا دور” کے“فسادات نمبر” سے شروع ہوا۔ اسی خاص نمبر کو توسیع دے کر ممتاز شیریں نے“ظلمت نیم روز” کے نام سے ایک کتاب مرتب کی جسے اشاعت کے لیے پاکستانی ادیبوں کی سرکاری تنظیم پاکستان رائٹرز گلڈ کے حوالے کیا گیا۔ مسودے کی پُراسرار گمشدگی کے باعث یہ کتاب سرکاری خرچ پر نہ چھپ سکی۔ چوںکہ دو ڈھائی سو سال پرانے ان مخطوطوں کو دوبارہ جمع کرنا ممکن نہیں تھا اور اس مجموعے کو اپنے خرچ پر شائع کرنا ممتاز شیریں کی استطاعت سے باہر تھا، اس لیے اسے ان کی وفات کے بعد ان کے برخوردارِ سعادت آثار آصف فرخی نے از سرِ نو مرتب کرکے شائع کرایا۔ پے در پے اشاعتوں کے باوجود یہ سوال کرنے کی مجال کسی کو نہیں ہوئی کہ عسکری کا موقف ان انتخابات میں شامل افسانوں، مثلاً “کھول دو“،“لاجونتی” اور“گڈریا” کی موجودگی میں کس طرح قابلِ اعتبار ٹھہرتا ہے۔
عسکری کے تابعینِ مہمل سے یہ توقع کرنا انصاف سے بعید ہو گا کہ ان کے نقادانہ جلووں کے سامنے اپنی آنکھیں خیرہ نہ ہونے دیں۔ ان کی خوش عقیدگی کا عالم دیکھ کر تو ضمیر جعفری کی نظم یاد آجاتی ہے جس کا ذیلی عنوان”ایک ژولیدہ گفتار بزرگ کے دھندلے دھندلے ملفوظات کا خلاصہ”ہے۔ (یہ نظم اُس وقت وقت بھی بےساختہ یاد آتی ہے جب عسکری کی تحریروں میں فراق گورکھپوری کا ذکر ہو رہا ہو۔) اس نظم کا ہر بند ٹیپ کے اس مصرعے پر ختم ہوتا ہے:۔
شاگرد بولا واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے!۔
ان کی توصیفی فقرے“اگر کوئی پوچھے۔۔۔” سے شروع ہوکر“ظاہر ہے عسکری صاحب” پر ختم ہوتے ہیں۔
superlatives
سے اِدھر رکنے کو یہ گستاخی گردانتے ہیں۔ “عسکری یہ بھی جانتے تھے کہ پودے کیسے زندہ رہتے ہیں اور ذروں میں ہستی کا کون سا قانون عمل کرتا ہے” کی قبیل کے فقروں کو تو خیر “پیراں نمی پرند” کی کرامات سمجھ کر نظرانداز کیا جا سکتا ہے۔ لیکن“فسادات کے ادب پر عسکری صاحب کا مضمون وقیع ترین ہے“، “عسکری صاحب اردو کے اعلیٰ ترین نقاد ہیں“، اس قسم کی باتیں اتنے تواتر کے ساتھ اور زور دے دے کر دُہرائی جاتی ہیں کہ سننے والے کو شبہ ہونے لگے کہ یا تو کہنے والے کو خود ان باتوں پر یقین نہیں ہے یا پھر اس کا اشارہ اردو تنقید کی کم مایگی کی طرف ہے۔
باقی نقادوں کا خیال غالباً یہ ہے کہ اعلیٰ ترین کا فیصلہ چونکہ قیامت تک کے لیے ہو ہی گیا ہے ، اور تنقید کی جو بلندترین سطح اردو ادب کے مقدر میں تھی وہ میسر آ ہی چکی ہے، اس لیے عسکری کی تحریروں کو غور سے پڑھنے اور ان کے بارے میں سوال اٹھانے سے کیا حاصل۔ یا ممکن ہے نقادوں کو تازہ افسانوں کے پرچہ ہائے ترکیب استعمال لکھنے سے فرصت نہ ملتی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انھیں اپنی پگڑی کے اچھالے جانے کا خوف عسکری کی تحریروں کا تجزیہ کرنے سے باز رکھتا ہو۔
واقعہ یہ ہے کہ بعض پڑھنے والوں کے ذہن میں عسکری کی تنقید پڑھ کر کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور چونکہ پڑھنے والوں کے سر پگڑی سے آزاد ہوتے ہیں اس لیے وہ ان سوالوں کا سامنا کرنے سے نہیں جھجھکتے۔ پھر وہ اس کو کوئی غیرمعمولی یا خلافِ وضعِ فطری بات بھی نہیں سمجھتے کہ اہم نقادوں کے معاملے میں کبھی کبھار ایسے سوال پیدا ہوں۔ اگر اہم نقاد بڑا نقاد بھی ہوا تو ان سوالوں سے نمٹنے کے بعد بھی اس کی تحریروں میں کچھ نہ کچھ بچ رہے گا جو پڑھنے والوں کے کام کا ہو گا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو بھی کیا حرج ہے۔
“فسادات اور ہمارا ادب” نامی مضمون چند ایسے موضوعات کو براہِ راست یا بالواسطہ طور پر زیر بحث لاتا ہے جن سے عسکری کو اس مضمون سے پہلے اور بعد میں اکثر سروکار رہا ہے، مثلاً ادیب کی ذمے داری، خارجی حالات سے ادب کا تعلق، آزادی فکر، تنقید کا منصب، ادبی منصوبہ بندی وغیرہ۔ اس بنا پر اس تحریر کو عسکری کی دوسری تحریروں کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش شاید نامناسب نہ ہو۔
♠

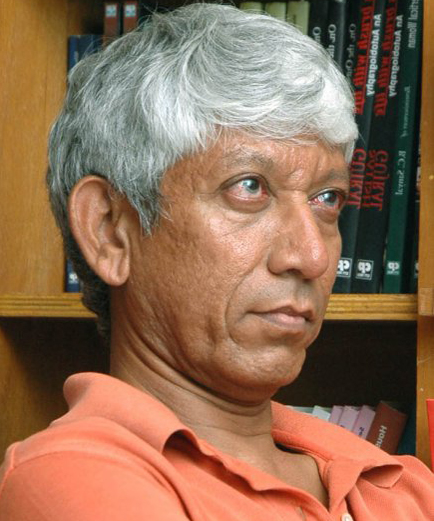




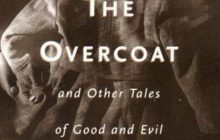





















Pingback: نقاد کی خدائی۔2:عسکری اور فسادات کا ادب – Niazamana