اجمل کمال
مئی ۱۹۴۶ کے بعد محمد حسن عسکری نے جو سیاسی موقف اختیار کیا اور اسے ادب پر جس طرح منطبق کرنے کی کوشش کی، اس کے سلسلے میں انھیں ایسی تحریروں کی سخت ضرورت تھی جنھیں وہ اپنے نووضع کردہ ادبی نظریے کی مثال کے طور پر پیش کر سکیں۔ منٹو کو ترقی پسندوں سے الگ قراردینا عسکری کی اسی (ادبی؟) ضرورت کا شاخسانہ تھا، ورنہ ان کے پاکستانی ادب کے خزانے میں صرف ’’یا خدا‘‘ کا نام رہ جاتا۔
عسکری اور ان کے ہم خیال نقادوں، خصوصاً ممتاز شیریں، کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ وہ منٹو کے اندازِ فکر سے قربت رکھتے ہیں، چنانچہ ان کی تنقیدی تحریروں کی معنویت کو سمجھنے میں مددگار ہو سکتی ہیں۔ میری رائے میں یہ تاثر غلط فہمی پر مبنی اور قطعاً بےبنیاد ہے۔ میں اس باب میں اپنی اسی رائے کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔
عسکری کی تحریروں میں منٹو کے لیے والہانہ پسندیدگی پاکستان بننے سے پہلے کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ جنوری ۱۹۴۶ کی ’’جھلکیاں‘‘ میں لکھتے ہیں:۔
۔’’نئے ادب کی تحریک میں میں بھی شامل رہا ہوں اور اب اس تحریک میں چند سانس اور باقی رہ گئے ہیں، وہ بھی اکھڑے اکھڑے۔ یہ سارا ہنگامہ محض بلوغت کا ابال تھا اور زمانۂ بلوغت لازوال نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ پچھلے دس سال میں اس تحریک نے جو ادب پیدا کیا ہے وہ صرف انڈرگریجویٹ ادب ہے۔ عصمت چغتائی کے مضمون ’’دوزخی‘‘ کو چھوڑ کر (ایسی ایک آدھ چیز اور ہو تو اس وقت یاد نہیں آ رہی) اس ادب میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو سنجیدہ ذوق رکھنے والے دماغ کو زیادہ دیر تک مصروف رکھ سکے۔ میٹھا برس لگتا ہے تو اسکول کی لونڈیاں تک ایسا ادب پیدا کر لیتی ہیں‘‘۔
یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ منٹو کے جو افسانے اس وقت تک شائع ہو چکے تھے ان میں ’’نیا قانون‘‘، ’’ہتک‘‘، ’’خوشیا‘‘، ’’دھواں‘‘، ’’بو‘‘ اور ’’کالی شلوار‘‘ شامل تھے جنھوں نے ’غیرسنجیدہ‘ ذوق رکھنے والے دماغوں کو خاصی دیر تک مصروف رکھا تھا۔ اگر ۱۹۴۶ میں عسکری کے نزدیک منٹو کا یہ سارا کام دریابُرد کر دینے کے لائق ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دو سال بعد کس بنیاد پر انھیں اتنا اہم ادیب قرار دینے لگتے ہیں؟
دستیاب شہادتوں کی روشنی میں اس بات پر یقین کرنے کا خاصا جواز موجود ہے کہ عسکری اور ان کی شاگردہ ممتاز شیریں کی منٹو سے وابستگی کی وجہ موقع پرستی کے سوا کچھ نہیں تھی۔ (موصوفہ بھی منٹو پر ۱۹۴۷ کے بعد ہی فریفتہ ہوئیں۔) عسکری کو منٹو پر قبضہ جمانے کا موقع اس وقت ملا جب ترقی پسندوں کے ایک اجلاس نے ایسے ادیبوں اور ادبی رسالوں کا بائیکاٹ کرنے کی احمقانہ قرارداد منظور کی جو ان کی تنگ نظر تعریف کی رو سے غیرترقی پسند ٹھہرے تھے۔ اس قرارداد کی مدافعت کسی بھی طرح نہیں کی جا سکتی۔
منٹو کی تحریروں کے مطالعے کی بنیاد پر میرے نزدیک منٹو کو غیرترقی پسند قرار دینا کسی طرح ممکن نہیں ہے، خواہ اسے ثابت کرنے کے لیے ترقی پسند اور عسکری مل کر ہی کیوں نہ زور لگائیں۔ اس کی تصدیق اس حقیقت سے بھی ہوتی ہے کہ آزادی کے بعد کے ابتدائی برسوں میں منٹو اور ترقی پسند آزادی اظہار کے جرم میں کٹہرے میں ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ منٹو کے جن افسانوں پر ’’قوم‘‘ نے سخت گیری کی وہ (بائیکاٹ کی قرارداد کے باوجود) ترقی پسند رسالوں ہی میں چھپے تھے۔
آئیے تقسیم کے بعد ترقی پسندوں اور عسکری کے سیاسی موقف کا جائزہ لیں اور پھر یہ دیکھیں کہ منٹو کا سیاسی موقف ان دونوں میں سے کس کے زیادہ نزدیک ہے۔ ترقی پسندوں کا خیال غالباً فیض کی نظم ’’صبحِ آزادی‘‘ میں سب سے زیادہ معروف طور پر بیان ہوا ہے جو ’’یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر‘‘ سے شروع اور ’’چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی‘‘ پر ختم ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ مئی ۱۹۴۶ میں مسلم لیگ کی حمایت کا فیصلہ کرتے ہوے عسکری نے پاکستان کے بارے میں کیسی ’’خوش اندیشانہ‘‘ توقعات ظاہر کی تھیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عسکری کی یہ توقعات پوری ہوئیں یا نہیں۔ ستمبر ۱۹۴۸ء کی ’’جھلکیاں‘‘ میں لکھتے ہیں:۔
۔’’پاکستان بننے کے بعد مسلمان شاعروں نے پاکستان کا خیرمقدم جس خوبصورتی سے کیا ہے وہ بھی داد کے قابل ہے۔ ہمارے شاعروں کو گلہ ہے کہ ہم نے تو نہ جانے کیا کیا خواب دیکھے تھے اور تعبیر بالکل الٹی ہوئی۔ ابھی ہماری منزل نہیں آئی، ہمیں تو بہت دور جانا ہے! آپ کو دیکھیے اور آپ کے خوابوں کو دیکھیے! جیسے تاریخ کو چاہیے تھا حرکت کرنے سے پہلے آپ سے مشورہ کر لیتی کہ لو بھئی، اب میں آگے کھسکتی ہوں، بولو مزدوروں کی اجرت میں پانچ فی صدی اضافہ کرواتے ہو یا دس فی صدی۔ تو جناب، اگر ہمارے شاعر حضرات کی منزل ابھی نہیں آئی تو خدا انہیں ہمت سفر دے، ہم تو ان کے خیرخواہوں میں سے ہیں۔ باقی رہی مسلمان قوم، تو اس کی منزل تو آ گئی، بلکہ اس کی منزل تو اسی دن آ گئی تھی جس دن قوم کے دل میں اپنی ہستی اور انفرادیت کو قائم رکھنے کا احساس پیدا ہوا تھا۔ قیام پاکستان اور اس کے بعد جتنی بھی باتیں ہوں وہ تو سب تفصیلات ہیں۔ قوم نے اپنے آپ کو پا لیا، قوم کی منزل آ گئی۔ ہاں، ویسے اگر آپ کو چلنے ہی کا شوق ہو تو بسم اللہ، پائے مرا لنگ نیست‘‘۔
سبحان اللہ!۔
عسکری کا خیال ہے کہ جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ منزل ابھی نہیں آئی وہ قوم کی امنگوں سے بےاعتنائی کا ثبوت دے رہے ہیں اور اگر قوم ان کے ساتھ سخت گیری کرے تو بالکل حق بجانب ہو گی۔ لیکن اُس پروگرام کا کیا ہوا جس کی رو سے پاکستان کو ایک عوامی اور اشتراکی ریاست بننا تھا، سرمایہ داری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا تھا اور مستقل امن و امان قائم کرنا تھا؟ ایسے احمقانہ اور گستاخانہ سوال صرف ترقی پسند کیا کرتے ہیں جو مسلمان کو گمراہ کر کے پاکستان سے بدظن کرنا چاہتے ہیں۔
اب ذرا ایک اور اقتباس کی طرف توجہ کیجیے:۔
۔’’۱۴ اگست کا دن میرے سامنے بمبئی میں منایا گیا۔ پاکستان اور ہندوستان دونوں آزاد ملک قرار دیے گئے تھے۔ لوگ بہت مسرور تھے، مگر قتل اور آگ کی وارداتیں باقاعدہ جاری تھیں۔ ہندوستان زندہ باد کے ساتھ ساتھ پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگتے تھے۔ کانگریس کے ترنگے کے ساتھ اسلامی پرچم بھی لہراتا تھا۔ پنڈت جواہرلال نہرو اور قائداعظم محمد علی جناح دونوں کے نعرے بازاروں اور سڑکوں میں گونجتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہندوستان اپنا وطن ہے یا پاکستان، اور وہ لہو کس کا ہے جو ہر روز اتنی بےدردی سے بہایا جا رہا ہے۔ وہ ہڈیاں کہاں جلائی یا دفن کی جائیں گی جن پر سے مذہب کا گوشت چیلیں اور گدھ نوچ نوچ کر کھا گئے تھے۔ اب کہ ہم آزاد ہوئے ہیں، ہمارا غلام کون ہو گا؟ جب غلام تھے تو آزادی کا تصور کر سکتے تھے۔ اب آزاد ہوئے ہیں تو غلامی کا تصور کیا ہو گا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم آزاد بھی ہوئے ہیں یا نہیں؟ ہندو اور مسلمان دھڑادھڑ مر رہے تھے۔ کیسے مر رہے تھے؟ کیوں مررہے تھے؟ ان سوالوں کے مختلف جواب تھے، ہندوستانی جواب، پاکستانی جواب، انگریزی جواب۔ ہر سوال کا جواب موجود تھا، مگر اس جواب میں حقیقت تلاش کرنے کا سوال پیدا ہوتا تو اس کا کوئی جواب نہ ملتا۔
۔’’ہندوستان آزاد ہو گیا تھا۔ پاکستان عالم وجود میں آتے ہی آزاد ہو گیا تھا۔ لیکن انسان ان دونوں مملکتوں میں غلام تھا۔ تعصب کا غلام، مذہبی جنون کا غلام، بربریت کا غلام‘‘۔
یہ کون شخص ہے جس کو اتنا بھی پتا نہیں کہ مسلمان قوم کی منزل تو کب کی آ گئی؟ ضرور کوئی ترقی پسند ہو گا۔
جی ہاں، یہ منٹو ہے۔ یہ اقتباس اداکار شیام کے خاکے ’’مرلی کی دھن‘‘ سے لیا گیا ہے جسے منٹو نے ہجرت کر کے پاکستان آنے کے بعد لاہور میں بیٹھ کر لکھا تھا۔ ملاحظہ کیجیے کہ عسکری اتنا واضح موقف رکھنے والے منٹو کو ترقی پسندی سے دور اور اپنی ’’خوش اندیشیوں‘‘ کے قریب بتاتے ہیں۔
مظفر علی سید کا کہنا ہے کہ منٹو کے افسانوں پر مقدمے یوں تو فحاشی کے الزام میں قائم کیے گئے لیکن اصل اعتراض منٹو کے سیاسی موقف پر تھا۔ اوپر دیے گئے اقتباس سے بھی یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ ریاست کے لیے منٹو کے سیاسی خیالات کو برداشت کرنا بہت دشوار تھا کیونکہ اس قسم کے خیالات ’’قوم‘‘ کی امنگوں سے بےاعتنائی کا مظہر ہیں اور بقولِ عسکری ’’قوم‘‘ اگر ایسے خیالات رکھنے والوں سے سخت گیری برتتی ہے تو حق بجانب ہے۔ لیکن مظفر علی سید کے برخلاف، عسکری اور ممتاز شیریں کے نزدیک منٹو کے سیاسی خیالات ریاست کے لیے بالکل قابل قبول اور ترقی پسندوں کے موقف سے بالکل الگ ہیں۔
جہاں تک ممتاز شیریں کا تعلق ہے تو ان کی تنقید کی پرواز ان کی تحریروں میں پائے جانے والے ان نادر نکتوں سے ظاہر ہے جن کی نامعلوم گہرائیوں پر ان کے مداحین اور وابستگان آج تک سر دُھنتے دیکھتے جاتے ہیں۔ ’’منٹو کا انسان نوری ہے نہ ناری، وہ آدم خاکی ہے۔‘‘ یہ انھوں نے منٹو کی منفرد خصوصیت دریافت کی ہے۔ گویا مثال کے طور پر عظیم بیگ چغتائی، بیدی اور غلام عباس کے کردار یا تو نوری ہوتے ہیں یا ناری۔ یہ ایسا زبردست انکشاف تھا کہ منٹو کے بارے میں شیریں کی کتاب، جسے انھوں نے اپنی زندگی میں شائع کرنا مصلحت کے خلاف جانا تھا، ان کی وفات کے بعد آصف فرخی نے مرتب کر کے ’’نوری نہ ناری‘‘ ہی کے عنوان سے شائع کی۔
ایسا ہی ایک نکتہ منٹو کی کہانی ’’سڑک کے کنارے‘‘ پر ان کے مضمون سے برآمد ہوتا ہے۔ اس افسانے کا حاصل ممتاز شیریں کے الفاظ میں یہ ہے: ’’ایک عورت، ایک ماں کی زخمی پھڑپھڑاتی ہوئی روح‘‘۔ یہ بھی خاصا کارآمد نکتہ ہے۔ اس ناقدانہ پھڑپھڑاہٹ کی مدد سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ’’نیا قانون‘‘ میں ایک کوچوان کی زخمی پھڑپھڑاتی ہوئی روح ملتی ہے اور ’’ٹوبہ ٹیک سنگھ‘‘ میں ایک پاگل کی زخمی پھڑپھڑاتی ہوئی روح۔
مزید فرماتی ہیں، ’’منٹو کے افسانوں میں عورت ترغیب مجسم ہے۔‘‘ منٹو کے افسانوں سے یہ جوے شیر نکالنے کے لیے فرہاد کا نہیں، شیریں کا جگر چاہیے۔ ظاہر ہے، سوگندھی، موذیل، سلطانہ اور مسز اسٹیلا جیکسن کو آپ ترغیب مجسم نہیں کہیں گے تو کیا ’’اپنی نگریا‘‘ میں ہنسی خوشی رہنے والی عفیفائیں قرار دیں گے؟ شیریں کے پاس لے دے کر ’’فطری انسان‘‘ اور ’’بنیادی گناہ‘‘ جیسے معصوم (اور سیاسی طور پر بےضرر) تصورات ہیں جن کی مدد سے وہ منٹو کو سمجھنا اور سمجھانا چاہتی ہیں۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا!
ممتاز شیریں تو خیر قابلِ معافی ہیں۔ ایک توبقول عسکری ان کی تاریخ ہی ان کی شہرت سے شروع ہوئی۔ دوسری وجہ ان کی سادہ خیالی ہے کہ ان کے نزدیک اردو ادب کی معراج بس یہ تھی کہ مغربی ادب کی ایک اچھی سی نقل بن جائے (اور مغربی ادب بھی بس اتنا جتنا ’’آکسفرڈ‘‘ میں پروفیسر ’’بیامبرو‘‘ سے پڑھا تھا اور پاکستان میں عسکری اور اپنے نیک نہاد شوہر سے سن لیا تھا)۔ بےچاری یہی سوچ سوچ کر نہال ہوتی رہتی تھیں کہ منٹو اردو افسانے کے موپاساں ہیں، بیدی چیخوف ہیں، قرۃ العین حیدر ورجینیا وولف ہیں، عزیز احمد آلڈس ہکسلے ہیں، احمد علی (لاحول ولاقوۃ) کافکا ہیں، وہ خود ایملی برونٹے ہیں اور ان کا ’’نیا دور‘‘ پنگوئن نیو رائٹنگ ہے! چلیے، خوش خیالی سے کسی کا کیا بگڑتا (یا بنتا) ہے۔ عسکری کا تخلیقی مانجھا جوانی ہی میں ڈھیلا نہ پڑ گیا ہوتا تو وہ اپنی خوش خصال شاگردہ کے ہاتھوں شاید چھوٹے موٹے جوئس یا لارنس بن گئے ہوتے۔
ممتاز شیریں کے ادبی کارناموں کی جانب چند اشارے ’’سوغات‘‘، بنگلور کے ایڈیٹر محمود ایاز نے اپنے رسالے کے شمارہ ۳ کے اداریے میں کیے۔ لکھتے ہیں:۔
۔’’ان کے جن چند مضامین میں زبان و بیاں کی کم زوریاں نہیں پائی جاتیں ان پر یہ گمان گزرتا ہے کہ یہ مضامین پہلے انگریزی میں لکھے گئے ہیں اور پھر کسی اچھے لکھنے والے سے ان کا اردو میں ترجمہ کرایا گیا ہے، مثلاً ’ادیب اور ذہنی آزادی‘ یا ’کشمیر اداس ہے‘ کے دیباچے کا وہ حصہ جو مسئلۂ کشمیر سے متعلق ہے۔ ان مضامین میں کوئی جھول نہیں ہے۔ ایسی نپی تلی نثر اور ایسی کفایتِ الفاظ کہ ہر سطر پر انگریزی کا دھوکا ہو۔ اظہار میں ایک روانی بھی ہے اور بیان کی قوت بھی۔ ان مضامین میں حوالوں سے اور دلائل کی بنیاد پر اپنے خیالات کی تائید میں جو زوردار مقدمے قائم کیے گئے ہیں، وہ ایک ایسے تربیت یافتہ ذہن کا پتا دیتے ہیں جو ممتاز شیریں کا یقیناً نہیں تھا۔ پاکستان آنے کے بعد ممتاز شیریں میں جو تبدیلی آئی یا لائی گئی اس کا ذکر تفصیل طلب بھی ہے اور اذیت ناک بھی، اور آج ان کی موت کے بعد یہ باتیں شاید کچھ زیادہ معنی نہیں رکھتیں۔ جبر و استحصال شاید ان کا مقدر تھا اور انہوں نے اسے بہ ظاہر ہنسی خوشی اور بغیر کسی مزاحمت (؟؟) کے اس طرح قبول کرلیا جیسے یہ ان کا اپنا منتخب کردہ راستہ تھا۔ ’میگھ ملہار‘ پر ’سوغات‘ کے تبصرے کی تلخی اور تندی کی وجہ یہی تھی۔ کیا لکھیں کیا نہ لکھیں اور کب لکھیں، یہ باتیں لکھنے والا اپنے طور پر طے کرتا ہے اور جب یہ فیصلے کوئی اور صادر کرنے لگے یا کسی پلاننگ اور منصوبہ بندی کے تحت یہ فیصلے کرنے پڑیں تو رفتہ رفتہ تخلیق کار کی موت ہو جاتی ہے۔ جسمانی موت تو بعد میں آتی ہے“۔
۔’’منٹو پر کتاب لکھتے لکھتے اچانک رک جانے کا سبب تلاش کرنے کے لیے علم غیب کی ضرورت نہیں۔ کوہِ ندا سے آنے والی آوازیں مختلف لوگوں کے لیے مختلف بلاوے لاتی ہیں، کسی کو وزارت کے تو کسی کو سفارت کے، ان بلاووں کا انتظار کرنے والوں کو ہمیشہ ’با ادب‘ اور ’با وضو‘ رہنا پڑتا ہے، چاہے زندگی بھر بلاوا نہ آئے۔ منٹو کو عسکری کی دوستی نے ’معزز‘ بنا دیا تھا، لیکن منٹو معزز بنا رہنے کے لیے تھوڑے ہی پیدا ہوا تھا۔ ’ٹھنڈا گوشت‘ پر مقدمے کے ساتھ صورت حال الگ ہو گئی ۔ اب کم از کم کچھ عرصے کے لیے ’نوری نہ ناری‘ کے خطرناک منصوبے کا التوا ضروری تھا! ’کفارہ‘ کو وہ اپنی بہترین تخلیق سمجھتی تھیں لیکن اس کے مفہوم و معنی کے بارے میں ان کو نظرثانی پر مجبور ہونا پڑا، کیونکہ کفارے کا عیسوی تصور غیراسلامی تھا!! ’آگ کا دریا‘ کے بارے میں ان کی رائے اچھی تھی لیکن کسی محفل میں وہ اس رائے کا اظہار نہیں کر سکتی تھیں (کم از کم ۶۱ میں)۔ ہر آدمی کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں جنہیں کوئی دوسرا سمجھ نہیں پاتا‘‘۔
خاصے سنگین الزامات ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ ’’ترقی پسندوں‘‘ کی طرف سے آئے ہوں جو پاکستان بننے کے بعد کمیونسٹ پارٹی کا اشارہ پا کر دن رات یہی رٹ لگائے رکھتے تھے کہ یہاں آزادیِ اظہار کا قحط ہے۔ آصف فرخی کو طلسم کشائی اور سرکاری ٹی وی کی منھ دکھائی کے دلچسپ مشاغل سے کچھ وقت نکال کر ان الزامات سے ممتاز شیریں کے دفاع کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ آخر کچی عمر سے موصوفہ کے درِ دولت سے وابستہ رہے ہیں، کچھ تو حقِ برخورداری ادا کریں۔
خواہ آپ کو ممتاز شیریں سے اور ان کی ’’تخلیقات و تنقیدات‘‘ سے کوئی دلچسپی ہو یا نہ ہو، یہ لطیفہ آپ کو ضرور محظوظ کرے گا کہ کوئی شخص ’’ادب، ادیب اور ذہنی آزادی‘‘ کے موضوع پر کسی کے جبر کے تحت مضمون لکھے۔ تاہم محمود ایاز کے اداریے کے اس اقتباس سے اس گھٹی ہوئی فضا کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے جس نے رفتہ رفتہ منٹو کی جان لے لی۔
اردو کی مایۂ ناز ادیب اور نقاد ہونے کے علاوہ ممتاز شیریں کی ایک حیثیت ’’نیا دور‘‘ کی مدیرہ کی بھی تھی۔ ان کی ادارتی ترجیحات اور محرکات کم و بیش وہی ہیں جن کا اندازہ آپ کو محمود ایاز کے اداریے سے ہو گیا ہو گا۔ اس سلسلے میں ایک نکتے کی طرف منٹو نے اپنے مجموعے ’’ٹھنڈا گوشت‘‘ کے ابتدائیے ’’زحمت مہر درخشاں‘‘ میں اپنے بےمثال انداز میں اشارہ کیا ہے:۔
۔’’اس دوران میں کراچی سے محترمہ ممتاز شیریں کے متعدد خط آ چکے تھے کہ میں ان کے ’نیا دور‘ کے لیے کوئی افسانہ بھیجوں۔ میں نے اٹھا کر ’ٹھنڈا گوشت‘ ان کو روانہ کر دیا۔ کافی دیر بعد جواب آیا کہ ہم دیر تک سوچتے رہے کہ اسے شائع کیا جائے یا نہیں۔ افسانہ بہت اچھا ہے، مجھے بہت پسند ہے لیکن ڈر ہے کہ حکومت کے احتساب کے شکار نہ ہو جائیں۔ ’ٹھنڈا گوشت‘ یہاں سے بھی ٹھنڈا ہو کر واپس میرے پاس پہنچ گیا‘‘۔
حکومت کے احتساب کا یہ خوف تنہا ممتاز شیریں تک محدود نہیں۔ عافیت کوشی کی یہ روایت شاہد احمد دہلوی (مدیر ’’ساقی‘‘) سے ان تک پہنچی ہے۔ شاہد احمد کی نازک مزاجی اور ٹکا سا جواب دے ڈالنے کی عادت اردو ادب کی صنمیات کا حصہ بن چکی ہے (اس صنم تراشی میں خود انھوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے)۔ شاہد احمد کی شاہکار کتاب ’’گنجینۂ گوہر‘‘ میں شامل منٹو کے خاکے کے یہ دو اقتباسات ملاحظہ کیجیے:۔
۔’’میں منٹو ہوں، سعادت حسن۔ آپ نے ’ہمایوں‘ کا روسی ادب نمبر دیکھا ہو گا۔ اب میں ’ساقی‘ کا فرانسیسی ادب نمبر نکالنا چاہتا ہوں۔
پہلی ہی ملاقات میں اس کی یہ ضرورت سے بڑھی ہوئی بےتکلفی طبیعت کو کچھ ناگوار گزری۔ میں نے اس کا پانی اتارنے کے لیے پوچھا، ’آپ کو فرانسیسی آتی ہے ‘۔
بولا،’نہیں!‘۔
میں نے کہا، ’تو پھر آپ کیا کر سکیں گے؟‘۔
منٹو نے کہا، ’انگریزی سے ترجمہ کر کے میں آپ کا یہ خاص نمبر ایڈٹ کروں گا‘۔
میں نے کہا، ’اپنا پرچہ تو میں خود ہی ایڈٹ کرتا ہوں۔ پھر ’’ساقی‘‘ کے چار خاص نمبر مقرر ہیں۔ ان کے علاوہ اور کوئی نمبر فی الحال شائع نہیں ہوسکتا‘۔
منٹو نے دال گلتی نہ دیکھی تو فوراً اس موضوع ہی کو ٹال دیا۔
۔’’دلی آنے کے بعد منٹو کی افسانہ نگاری کا دور جدید شروع ہوا۔ انہوں نے طبع زاد افسانے ایک اچھوتے انداز میں لکھنے شروع کیے۔ ’ساقی‘ کے لیے ہر مہینے ایک افسانہ بغیر مانگے مل جاتا۔ ’دھواں‘ اسی ریلے میں لکھا گیا اور اس کی اشاعت پر دلی کے پریس ایڈوائزر نے مجھے اپنے دفتر بلوایا۔ وہ پڑھا لکھا اور بھلا آدمی تھا۔ انگریزی ادبیات میں میرا ہم جماعت بھی رہ چکا تھا۔ بولا، ’بھائی! ذرا احتیاط رکھو۔ زمانہ برا ہے۔‘ بات آئی گئی ہو گئی۔ میں نے منٹو سے اس کا ذکر کیا۔ حسب عادت بہت بگڑا مگر ’ساقی‘ کے باب میں کچھ احتیاط برتنے لگا‘‘۔
آپ نے دیکھا، ’’اپنا پرچہ تو میں خود ہی ایڈٹ کرتا ہوں‘‘ کی ہیکڑی اور اپنے مخاطب کا ’’پانی اتارنے‘‘ کی للک پریس ایڈوائزروں کے سامنے کس طرح پانی بن کر بہہ جاتی ہے اور بات کیسے آئی گئی ہو جاتی ہے۔ منٹو کو یہ بات بھانپنے میں زیادہ دیر نہیں لگی ہو گی کہ شاہد احمد اپنا پرچہ خود ہی ایڈٹ کرتے ہیں اور پریس ایڈوائزروں کے سوا کسی کی مجال نہیں کہ ان کے ادارتی فیصلوں میں دخل دے سکے۔
پریس ایڈوائزروں اور ان کی ہدایات کو مشعل راہ بنانے والوں کے ہاتھوں منٹو کو آگے چل کر اور بہت کچھ بھگتنا تھا، اور انھیں خوب اندازہ تھا کہ آزادیِ اظہار کی اس لڑائی میں کون پریس ایڈوائزروں کے ساتھ ہے اور کون منٹو کے۔ افسوس، شاہد احمد نے دلّی کے اس بھلے مانس پریس ایڈوائزر کا نام نہیں لیا ورنہ وہ بھی اردو ادب کی تاریخ میں اسی طرح محفوظ ہو جاتا جیسے لاہور کے پریس ایڈوائزر چودھری محمد حسین کا نام منٹو کی کتاب ’’لذت سنگ‘‘ کے دو ایڈیشنوں کے انتسابوں کے باعث امر ہو گیا۔ چودھری صاحب پھر بھی اس لحاظ سے کم مضر تھے کہ انہیں پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت منٹو پر مقدمے چلانے کی سفارش کرنے کے ساتھ ساتھ خود کو منٹو کا مربی مشہور کرنے کا شوق نہ تھا۔
منٹو کا پالا تو کہیں زیادہ شوقین لوگوں سے پڑا تھا جن کا نقشِ قدم جناب شیخ کی طرح یوں بھی ہوتا ہے اور ووں بھی، مثلاً عسکری، جو منٹو کے سرپرست بھی ہیں اور ساتھ ساتھ پبلک سیفٹی ایکٹ کی حمایت بھی اس شدومد سے کرتے ہیں کہ ’’جنگ‘‘ اور ’’نوائے وقت‘‘ کے درباری کالم نگار تک شرما جائیں۔ اور پھر تربیت یافتہ ذہن رکھنے والوں کے لکھے ہوے مضامین اپنے نام سے شائع کرانے والی ممتاز شیریں اور اپنا رسالہ خود ایڈٹ کرنے والے شاہد احمد ہیں جو منٹو کے غیرمحتاط افسانوں کو شائع کرنے سے تاعمر محترز رہے کہ زمانہ برا ہے، لیکن اس سلسلے میں بائیکاٹ کا اعلان کرنے کی حماقت سے گریز کیا تاکہ بعد میں، سازگار زمانہ آنے پر، منٹو کی شخصیت اور فن پر مضامین لکھ کر شہرت بھی حاصل کی جا سکے۔
چودھری محمد حسین کے ان جانشینوں نے جہاں کہیں موقع پایا، منٹو کو اپنے کسی نہ کسی مقصد کے لیے استعمال کرنے کی دلاورانہ کوشش کی۔ یہ سلسلہ عسکری کے ہاتھوں منٹو کی تحریروں کی غلط تعبیر سے شروع ہوا اور اس کی چند برس پہلے کی ایک مثال وہ ہے جب منٹو کو ’’معزز بنانے‘‘ یا ان کی تحریروں کا دف مارنے کی کوشش کے سلسلے میں سنسرشپ کی قینچی کی مدد سے ’’نیا قانون‘‘ کا ایک نیا روپ تیار کیا گیا تاکہ اسے قوم کے نونہالوں کی تعلیم کے لیے استعمال کیا جاسکے۔ ’’نیا قانون‘‘ کے اس اصلاح یافتہ روپ سے لطف اور عبرت حاصل کرنے کا موقع آپ کو اگلے باب میں ملے گا، فی الحال کہانی کو آغاز سے شروع کرتے ہوے یہ ملاحظہ کیجیے کہ عسکری کے ہاتھوں منٹو کا کیا حشر ہوا۔
۔(جاری ہے)۔
♦






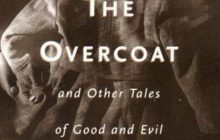





















Pingback: منٹو کی غلط تعبیر-2 – Niazamana
Pingback: منٹو کی غلط تعبیر۔آخری حصہ – Niazamana