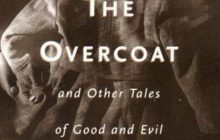ڈاکٹر برکت شاہ کاکڑ
بیسویں صدی سیاسی شورشوں اور انقلابات کیلئے تو زرخیز تھی ہی، لیکن یہ صدی ہر لحاظ سے ایک مردم خیز صدی بھی واقع ہوئی ہے۔ ہمارے ادب اور سیاست پر انمٹ نقوش چھوڑنے والوں میں سے زیادہ تر کی ولادت پہلی اور دوسری عالمی جنگ سے پہلے ہوئی ہے، اور جب برصغیر پاک و ہند میں استعماری نظام کے خلاف عوامی سیاسی تحریکیں چلنا شروع ہوئیں ، قید و بند کا سلسلہ شروع ہوا، دار کی خشک ٹہنیاں لیلیٰ وطن کے عشاق کے سروں سے بار آور ہوئیں، تو اس صورتحال نے ایسے افراد پیدا کئے جن کی عزم کے سامنے سینکڑوں سالوں کی لوٹ مار اور استعماریت کا دیوہیکل ڈھانچہ ریت کا قلعہ ثابت ہوا۔
تقسیم ہند کے بعد جب ملکی سطح پر جمہوریت کے استحکام اور فیڈریشن میں حصہ دار قومیتوں کے حقوق اور نمائندگی کیلئے سیاسی تحریکیں چل نکلیں تو ایسا ہی لگا جیسے مقتدر اور دست نگر طبقات کے درمیان کشمکش کا نیا باب کھل گیا ہو۔ بلوچستان کی سطح پر خان شہید عبدالصمد خان نے جو ضد سامراجی تحریک شروع کر رکھی تھی اُس نے ہند وستان میں آزادی کیلئے برپا تحریکوں کی صف میں اس خطے کی بھرپور نمائندگی کا حق پورا کیا۔انگریز استعمار یت کی بساط لپٹانے کیلئے ایک طرف سے مقامی سطح کی کامیاب سیاسی کاوشیں شروع ہوئیں تو دوسری طرف اشتراکی نظام کے خوف سے سرمائے کی سرد مہری پگھلنے لگی۔
یہاں جنوبی پشتونخوا (شمالی بلوچستان)کے قرب و جوار میں سینکڑوں سالوں پر محیط قبائلی سماج کے بند کواڑوں پر بھی دور جدید کی سیاسی اور سماجی تْقاضوں نے دستکیں دینا شروع کئیں ۔قبائلیت چونکہ جدید قومی ریاست کے ادارہ جاتی اور انتظامی بندشوں سے انحراف میں نشوونما پاتی ہے، اور انگریز سرکار (اور تقسیم ہند کے بعد بھی) اکثر پشتون علاقوں کو ایسے مخصوص قبائلی جبرمیں رکھا گیاجس نے کلچر کے تخلیقی اور اقداری روح کو شدید انداز میں متاثر کیا۔
چونکہ یہاں پر سماجی ڈھانچہ قبائلی خطوط پر استوار تھا، لہٰذا جدید سیاسی نظریات اور قومی ریاست کے ساتھ چلنے کی بنیادی سیاسی آگہی کافی حد تک کم تھی ۔ اس صورتحال میں چند اک تعلیم یافتہ نوجوانوں نے ہی قومی شناخت، تشخص ،حقوق اور وسائل پر اپنے اختیار کیلئے سیاسی عمل کی طرف سنجیدگی اور غیر مشروط وابستگی کے ساتھ رجوع کیا۔
پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد عددی لحاظ سے کم قومیتوں کے حقوق، نمائندگی اور شناخت کے جو مسائل رونما ہوئے، اس کیلئے اتنی ہی جدوجہد درکار تھی جتنا کہ انگریز استعمار سے آزادی حاصل کرنے کیلئے تھی۔ خان شہید عبدالصمد خان کی زندگی یک گونہ کاوشیں اور استقامت کے سبب اگرچہ ان کی نصف زندگی قید و بند میں گزری، لیکن ان کی تحریک اور جدوجہد نے پشتون قبائلی سماج کے بطن سے چند ایسے کردار تراشے جنہوں نے زندگی بھرعلم ، سیاست اور آدرش پسندی کی لو جلائے رکھی۔
عبدالرحیم مندوخیل اُن چند تعلیم یافتہ قبائلی نوجوانوں میں سے تھے جنہوں نے قومی شناخت ، وسائل، حقوق اور نمائندگی کو بطور مسئلہ جانا۔ ژوب میں اپنے آبائی گاوں اومژہ سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ گورنمنٹ سائنس کالج کوئٹہ کارخ کرتے ہیں اور اس کے بعد۱۹۶۳ میں پشاور یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ اسکے بعد لکھنے پڑھنے، نوجوان سیاسی کارکنان کی تربیت اورسیاسی تنظیم کے کام سے ایسے وابستہ ہوئے کہ پھر کسی اور طرف دھیان نہیں گیا۔
مجھے پہلی دفعہ ۱۹۸۸ میں انہیں ایک سیاسی جلسے کو دیکھنے کا موقع ملا، اس عمر میں ویسے بھی جلسے کو میلہ سمجھ کر شرکت ہواکرتی تھی۔ ضیاوالحق کے آمرانہ دور کا خاتمہ ہوچکاتھا اوراس سال پت جڑ کی موسم میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر پہنچ چکی تھیں۔ ہم سے قدرے سنئیر طلبا کوساری سیاسی تنظیموں کے نام اور لیڈروں کا علم تھا جبکہ مجھ تک صرف باچا خان اور خان شہید عبدالصمد خان کے کچھ مبہم قیصے کہانیاں پہنچی تھی۔ جس جلسے میں ہم نے شرکت کی اُس میں رحیم صاحب کی تقریر ہی یاد رہ گئی ۔
مجھے یاد ہے کہ جب رحیم صاحب نے تقریر شروع کی تو اس وقت کے ( موجودہ) صورتحال کا ایک تاریخی نقشہ کھینچنا شروع کیا، قومی محکومی کو مخصوص سامراجی عمل سے جوڑتے ہوئے جن کرداروں کے نام اور مخصوص تاریخی کردار پر انہوں نے بات کی، اس میں بجز جلال الدین اکبر اور اورنگزیب عالمگیر کے مجھے کسی کا علم نہ تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے شیر شاہ سوری، پیر روشان، خوشال خان خٹک، احمد شاہ ابدالی، غازی عبداللہ خان، شاہ شجاع، دوست محمد خان ، وزیر اکبر خان سارے ایسے نام تھے جس کا تذکرہ میں نے نہیں سنا تھا یہاں تک کہ کسی مہمان داستان گو نے بھی ان کرداروں کا ذکر نہیں کیا تھا۔
اگرچہ تاریخ میں میری دلچسپی فوک لوری اور قبائلی نوعیت کی تھی، مجھے کئی ایسے مقامی کرداروں سے منسوب قصے، واقعے اور دوہئے (غاڑی) یاد تھے جنہوں نے انگریز استعمار کے خلاف منظم اور مصمم مبارزہ کیا تھا۔ لیکن ان ناموں کے بارے میں نہ تو ہمارے درسی کتابوں میں کچھ ملتا تھا اور نہ ہی ہمارے اجتماعی فوک لوری یادداشت اتنی پائیدارواقعہ ہوئی تھی جو دو سو سال پہلے کے واقعات کو کسی نہ کسی انداز میں محفوظ رکھ سکے۔
اس کے بعد جب بھی میں نے رحیم صاحب کو سنا تو مجھے یہی احساس ہوا کہ وہ اپنی ماضی سے منقطع قوم کے خوابیدہ تاریخی شعور پر دستک دے رہے ہیں ۔پشتون اور دیگر محکوم قومیتوں کے وسائل اور ثقافتی و تہذیبی شناخت پر جب بھی بات کرتے تھے تو اس کا سرا مخصوص تاریخی حقیقتوں سے جوڑتے تھے ، اور پھر اس پر بھی سیر حاصل گفتگو ہوتی تھی کہ سماجی اور تاریخی حقیقتیں ہمیشہ انسانوں کی تخلیق کردہ ہوتی ہیں، اور انسان ہی اپنے منظم سیاسی اور سماجی کردار سے اسے تبدیل کرسکتے ہیں۔
رحیم صاحب کی سیاسی، تاریخی اور فلسفیانہ علم کا زیادہ تر مصرف نوجوان سیاسی کارکنان کی تربیت میں لگا۔ البتہ وہ ہمارے لئے آگہی پر مبنی پمفلٹ، مضامین اور مقالات کے ساتھ ساتھ دو ایسی کتابیں چھوڑ گئے ہیں جس میں ہم اُنکے علمیت، تنقیدی سوچ اور تجزیاتی مہارت کا صحیح ادراک کر سکتے ہیں۔
انہوں نے ۱۹۸۰ اور۱۹۹۰ کی دہائی میں سیاسی کارکنوں کی تربیت کیلئے منظم انداز سےایسے بے شمار لیکچرز دئے جن کے علم اور سیاست کے میدان میں انتہائی اہم تھے، لیکن ان لیکچرز کا تا حال کوئی ریکارڈ سامنے نہیں آیا۔ البتہ دسمبر ۲۰۰۳ تا دسمبر ۲۰۰۴ پانچ مفصل تاریخی لیکچرکا ایک سلسلہ چلا تھا اُس کا آڈیو ریکارڈ محفوظ کیا گیا تھا اور گذشتہ سال ہی رحیم صاحب کے قریبی شاگرد اور رفیق کار رضا محمد رضا صاحب کی کاوشوں سے بعنوان ‘‘ افغان اور افغانستان’’ زیور طباعت سے آراستہ ہوئی ہے۔
جب ہم ان پانچ لیکچرز کے موضوعات اور مشمولات دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ رحیم صاحب اس مخصوص خطے کی تاریخ پر اتنی دسترس رکھتے تھے کہ وہ پانچ سے سات گھنٹے تک ایک مخصوص موضوع پر لیکچر دیا کرتے تھے، انکی لیکچرز مبنی طبع شدہ کتاب افغان اور افغانستان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ رحیم صاحب چار ہزار سال کے تاریخی واقعات، کرداروں اور اس سے متعلق علمی منابع سے حیران کن حد تک واقف تھےاور انکے حافظے میں یہ تمام تر حوالے محفوظ تھے۔
علم تاریخ کو آپ نے اپنے ان منظم لیکچرز میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے۔
علم تاریخ سماج کے حرکی نظام سے مربوط ہوتا ہے ، اس میں اُن قوانین کا پتہ چلتا ہے کہ ایک معاشرہ کن خطوط پراستوار ہے اور کس سمت میں حرکت کرتا ہے۔ ہم تاریخ کے علم سے ایک سے عہد رفتہ کے انسانی سماج کا مکمل خاکہ کشید کرسکتے ـ (ترجمہ: افغان او افغانستان، ص۔4)۔
جب ۲۰ مئی کو ان کی رحلت کی خبر سنی تو آنکھوں کے سامنے عہد رفتہ کے کئی مناظر گھومنے لگ گئے ، انکا مخصوص پروقار لباس، لمبی لمبی تقریروں کے بیچ تکراری جملے، مخصوص کڑکدارمندوخیلی لہجہ، پچاس کے پیٹے میں بھی رومانوی دکھنے والا سفید بال، فلسفیانہ انداز گفتگو اور غضب کی سنجیدگی ، ایسے چیدہ چیدہ خصوصیات تھیں جو ان کو دور سے دیکھنے والوں کو بھی اپنا پتہ دے جاتے تھے۔
احساس زیاں تو ویسے بھی ہر بابرکت شخص کی وفات پر ہوتا ہے، لیکن رحیم صاحب تو شش جہت شخصیت تھے۔ سیاسی مدبر، مورخ، ماہر قانون، سیاسی نظریات کے معلم، تنقیدی شعور اور تجزیاتی مہارت سکھانے والا ایک باعمل منٹور۔ ان تمام عالمانہ اور ماہرانہ اوصاف کو اگر ایک طرف بھی رکھ دیا جائے، اور انکے روئیوں، عادات و خصلات، اور طرز زندگی پر اگر نظر دوڑائی جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ محض علم اور سیاست کو لازم و ملزوم نہیں سمجھتے تھے بلکہ تکلیف دہ حد تک سچائی اور دیانت داری بھی انکے کردار کا خاصا رہا ہے۔
انہوں نے سیاست میں اُصول اورعلم کو ذاتی ملکیت اور ملوکیت پر ترجیح دی۔کئی اہم اور بااثر سیاسی اور انتظامی عہدوں پر فائض رہے لیکن آخر تک خود کو بھی اور اپنے عزیز و اقارب کوبھی تہی دست ہی رکھا۔ رحیم صاحب نے زندگی کا بیشتر حصہ اپنے گھربار ، بال بچوں، عزیز و اقارب سے دُور رہ گزارا ۔ اُن کا مشن غیر سیاسی نوجوانوں کو سیاسی بنانا تھا تاکہ وہ اپنے مکمل انسانی اور فاعلی کردار سے آگاہ ہوں اور اُن حالات کو تبدیل کرسکیں جو انکےانسانی وجود اور حقوق کو تسلیم کرنے سے یکسر انکاری تھے ۔
تلخ حقیقت یہ ہے کہ اس قبیل کے سیاسی زعما اب کمیاب ہیں جو شہر اقتدار کی رعنائیوں میں سال ہا سال رہنے کے بعد بھی نان جوین پر قناعت کریں، جو مٹی کی خوشبو ، زُبان اور لہجوں کی چاشنی، شعراور ادب کے گُڑ کا ذائقہ، پُرانی کتابوں کی زرد پیلی صفحات میں برسوں کی مقید تاریخی سچائیوں کو زبان دینے ، اورخرد و جنون کی گتھیاں سُلجھانےمیں ہی خوش رہتے ہوں ۔
نہ فارن کرنسی اکاونٹس اور نہ ہی دوہری شہریت، ایسے تہی دست اُن بلند میناروں کی طرح ہوتے ہیں جو روشنیوں کے شہر کا پتہ دیتے ہیں، دور ہے ابھی کتنی صبح بتا دیتے ہیں۔ جن کی زندگی لوگوں اور کتابوں کے بیچ گزرے اور آخری ایام میں بیرون ملک علاج کیلئے جانے کے بجائے عوامی ہسپتال میں ایک عام شخص کی طرح داعی اجل کو لبیک کہے۔
♥