جب کراچی سے جہاز تربت کے لیے اڑا تو مسافروں میں اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو خلیج میں ملازمت کے لیے گئے ہوئے ہیں اور اب عید کے موقع پر اپنے گھر جارہے تھے۔ ان کے پاس گھر والوں کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے تھے۔ سامان کو رسیوں سے مضبوطی کے ساتھ باندھا ہوا تھا تا کہ محفوظ رہے۔ہوائی جہاز کا عملہ ان لوگوں سے کوئی تعاون نہیں کر رہا تھا۔ائیر ہوسٹس ایک بیزاری کے عالم میں ادھر سے ادھر جارہی تھی۔ غریب لوگ اگر جہاز پر بھی سفر کریں تب بھی ان کی عزت نہیں ہوتی ہے، حالانکہ کرایہ وہ پورا دیتے ہیں۔ جبکہ فوجیوں، صحافیوں اور پی آئی اے کے عملہ کے لیے آدھا یا اس سے زیادہ کرایہ معاف ہے۔ جہاز میں بھی مراعاتی اور غیر مراعاتی طبقوں کی تقسیم ہوتی ہے۔
کئی مرتبہ میرا تجربہ ہوا کہ یورپ آتے ہوئے جہاز کا عملہ بڑا تمیز دار ہوتا ہے مگر جیسے ہی دوبئی سے مزدور سوار ہوئے ، ان کا رویہ اور لہجہ بھی بدل جاتا ہے۔ ان غریب لوگوں میں بڑی قوت برداشت ہے۔ وہ اس سلوک کو خاموشی سے برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے میرا سفر کوئی خوشگوار نہ تھا۔ مگر جیسے ہی تربت کے ایئر پورٹ پر اترا، تو سامنے ایک نوجوان میری کتاب ’’تاریخ اور دانشور‘‘ لیے کھڑا میرا منتطر تھا۔ مجھے دیکھ کر گرمجوشی سے آگے بڑھا، میرا سامان لیا، اورنزدیک ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ ’’ اس کتاب پر کچھ لکھ دیجیے، بعد میں شاید آپ کو فرصت ملے یا نہ ملے‘‘۔ جب میں نے کتاب پر دستخط کر دیئے تو اس نے کہا کہ ’’ڈاکٹر مالک باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں‘‘۔
باہر ڈاکٹر مالک ہی نہ تھے ان کی جیپ بھی تھی، تربت آنے پر خوش آمدید کہااور ضد کرتے ہوئے گاڑی کی اگلی آرام دہ سیٹ پر مجھے بٹھایا۔ میں نے پوچھا کہ ان دوستوں کا کیا حال ہے جو بذریعہ بس کراچی سے تربت آئے ہیں کہنے لگے وہ صبح پانچ بجے پہنچے ہیں اور اب ہوٹل میں سو رہے ہیں۔
ہوٹل جاتے ہوئے میں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ چٹیل میدان، جگہ جگہ جھاڑیاں، بے آب و گیاہ زمین، کوئی رونق نہیں تھی۔ جدھر نظر دوڑاؤ وسیع میدان نظر آتا تھا۔ شہر میں داخل ہوئے تو کچے مکانات اور گلیاں تھیں۔ شہر میں بھی سڑکوں کا نام و نشان نظر نہیں آرہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں قرونِ وسطیٰ میں آگیا ہوں۔ میرے ذہن سے اچانک شہر کی رونق ، شاہرائیں ، چمک دمک غائب ہوگئی اور میں جدید زمانہ سے نکل کر ماضی کے قدیم دور میں داخل ہو گیا۔
مکران کا میرا یہ پہلا سفر تھا۔ اس کا انتظام بلوچستان نیشنل موومنٹ اور میوچل ایڈ سوسائٹی نے کیا تھا۔ میرا کراچی آنا ویسے تو ہوتا رہتا ہے مگر اس بار آغا خان یونیورسٹی میں لیکچر دینے آیا تھا۔ آغا خان یونیورسٹی کراچی کے مرکز میں واقع خوبصورت اور دلکش عمارت ہے۔ پوری عمارت ائیر کنڈیشنڈ ہے۔ کلاس رومز جدید طرز کے ہیں۔ اس کا نیا اسپورٹ سینٹر دیکھا تو معلوم ہوا کہ یورپ اور امریکہ میں آگیا ہوں۔ جمنازیم ، سوئمنگ پول، جاگنگ ٹریک اور پھر کیفے ٹیریا میں تازہ جوس۔
پاکستان میں ایسے جزیرے موجود ہیں کہ جو بقیہ آبادی سے کٹے ہوئے اپنے حصار میں قلعہ بند ہیں۔ معاشرہ اندرونی اور بیرونی دنیاؤں میں بٹا ہوا ہے جو جزیرے میں آباد ہیں۔ انھیں معلوم نہیں کہ باہر کیا ہورہا ہے۔ دونوں دنیائیں ایک دوسرے سے بے خبر اپنے آپ میں مگن ہیں۔ پھر یہ فرق شہروں میں ہی نہیں، صوبوں میں بھی ہے جس کا اندازہ مکران جا کر اور زیادہ ہوا۔ کہنے کو تو دنیا سمٹ رہی ہے۔ مگر پاکستانیوں کے لیے اس کے اپنے علاقے اور آبادیاں دور ہو رہی ہیں۔
کراچی سے تربت جانے کے لیے چودہ سے سولہ گھنٹے چاہییں کیونکہ دونوں شہروں کو ملانے کے لیے کوئی سڑک نہیں ہے۔ کچا راستہ ہے۔ میرے جو ساتھی بہترین بس میں سفر کرتے ہوئے چودہ گھنٹے میں تربت پہنچے ہیں تو ان میں سے کئی زخمی ہو چکے تھے، کیونکہ بس کے جھٹکوں نے انھیں نہ تو سونے دیا تھا اور نہ ہی صحیح و سالم رکھا تھا۔ ہوٹل پہنچنے پر ڈاکٹرمالک نے بتایا کہ تربت میں ہمارے پروگرام میں تین چیزیں ہیں۔ قریب ہی آثار قدیمہ کو دیکھنا کہ جہاں فرانسیسی ماہر آثار قدیمہ کام کررہے ہیں۔ اس کے بعد شہر کے خاص خاص لوگوں سے ملاقات اورلنچ اور عصر کو ہوٹل کے ہال میں لیکچر۔
چنانچہ سب سے پہلے ہم تربت کے باہر اس جگہ کو دیکھنے گئے کہ جہاں فرانسیسی ماہرین آثار قدیمہ نے ایک ٹیلہ کی کھدائی کی ہے۔ اس ٹیم کے سربراہ موسیورولینڈ ہیوال ہیں۔ ان کے ساتھ کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں فرانس سے ان کی مدد کو آئی ہوئی ہیں۔ انھوں نے مقامی لوگوں کو تربیت دے کر اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ احتیاط سے کھدائی کرتے ہیں اور زمین میں سے مدفون اشیاء کو باہر نکالتے ہیں۔ ٹیلہ میں کئی قبریں ملیں کہ جن میں مردہ دفن تھے۔ ان کے ساتھ دفن کیا ہوا سامان بھی ملا۔ یہاں سے جو کچھ ملتا ہے وہ کیمپ میں لے جاکر اس کی صفائی کرتے ہیں اور پھر اس کی تاریخ اور ہیت کے بارے میں تجزیہ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی پاکستانی ماہر نہیں کہ جو ان کے ساتھ مل کر تربیت حاصل کرتا۔ ٹیم کے ساتھ مقامی لوگ بڑا تعاون کر رہے ہیں۔
موسیو رولینڈ نے بتایا کہ وہ ایران اور مکران کے درمیان ثقافتی تسلسل کو دریافت کر رہے ہیں ، اور یہاں سے جو نتائج برآمد ہو رہے ہیں انھیں یورپ کے جرنلز میں شائع کراتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ۱۹۷۴ میں فرانسیسی ماہرین نے کچھی صحرا میں مہر گڑھ کے آثار دریافت کیے تھے۔ جو کہ بولان دریا کے خشک ہونے کے بعد ویران ہو گیاتھا۔ مہر گڑھ کی دریافت نے بلوچستان کی تہذیبی حیثیت کو بہت بڑھا دیا ہے۔ اس کی کھدائی کے بعد جو نتائج آئے وہ یہ تھے کہ مکانات کچی اینٹوں کے بنائے جاتے تھے۔ اناج کو ذخیرہ کر کے رکھا جاتا تھا اور معاشرہ مل کر اسے استعمال کرتا تھا۔ لوگ مردوں کو دفن کرتے تھے اور ان کے ساتھ ضرورت کا سامان بھی رکھ دیتے تھے۔
تربت کے قریب آثار کی دریافت اور اس کے نتائج بلوچستان کو اور زیادہ تہذیبی اہمیت کا بنا دیں گے۔ ان نتائج کے بعد بلوچستان کی تہذیب وادی سندھ کی تہذیب سے قدیم ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ان دریافتوں کے پیچھے پاکستانیوں کا ہاتھ نہیں ہے۔ یہ غیرملکی لوگ ہیں جو ہماری تاریخ کو تشکیل کرنے میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ اس سے ہمارے تعلیمی اداروں اور ریسرچ کے اداروں کی پس ماندگی ظاہر ہوتی ہے۔اہم بات تو یہ ہے کہ ان آثار کے بارے میں اب تک نہ تو پاکستان کے لوگوں کو علم ہے اور نہ ہی یہ نصاب کی کتابوں میں شامل ہیں۔ جبکہ بلوچستان کی نصاب کی کتابوں میں چاغی میں بم کے دھماکے فوراً شامل کرلیے گئے ہیں۔ آثار قدیمہ کی یہ دریافتیں یقیناًبلوچستان کے لوگوں میں تاریخی شناخت پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کریں گی۔
یہاں سے ڈاکٹر مالک ہم لوگوں کو اپنے فارم پر لے گئے ۔ چٹیل اور خشک ماحول میں اگر درخت اور پانی مل جائے تو ذہن بھی تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ درختوں کے سائے میں فرش پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ موسم خوشگوار تھا۔ آہستہ آہستہ لوگ آتے گئے۔ بحث رسمی بات چیت کے بعد سیاست پر آگئی۔ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ ملک کا کیا ہوگا؟ حالات کدھر جارہے ہیں؟ کیا بہتری کی کوئی امید ہے یا نہیں؟ حاضرین میں سے اکثر میڈیکل ڈاکٹر ، انجنیئر، وکیل اور کچھ سرکاری ملازمین تھے۔ سب ہی نے کراچی میں تعلیم پائی تھی۔ اس لیے ان کا کہنا تھا کہ کوئٹہ سے زیادہ ان کا تعلق کراچی سے ہے۔
تاریخی طور پر کبھی کراچی بلوچستان کا ہی حصہ تھا۔ وہاں اب بھی لیاری کے بلوچ یہاں ہی سے گئے ہوئے ہیں۔ جب بات سیاست کی ہوئی تو سب ہی نے پنجاب کی بالادستی پر تنقید کی اور سوال کیا کہ آخر کب تک پنجاب پاکستان پر حکومت کرے گا۔ میں نے کہا کہ ’’ذرا مسئلہ کو وسیع تناظر میں دیکھیں۔ قوم پرست تحریکیں اپنے سرداروں اور وڈیروں کو اپنا تسلیم کر کے ان کے مظالم اوران کے طبقاتی کردار کو بھول جاتی ہیں۔ قوم پرستی کا فائدہ ہمیشہ اعلیٰ طبقے اٹھاتے ہیں ۔ اس لیے پنجاب سے مقابلہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے حکمران طبقوں کی مخالفت کی جائے۔ اس کے عوام بھی استحصال شدہ ہیں۔ انھیں ساتھ ملا کر طبقاتی بنیادوں پر جدوجہد کی جائے‘‘۔
اس پر ایک ساتھی نے کہا کہ ’’ کیا پنجاب کے مظلوم طبقوں میں طبقاتی شعور بیدار کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے‘‘؟ اس جواب نے مجھے خاموش کر دیا۔ میں نے سوچا کہ کہاں ہیں وہ پنجاب کے دانشور کہ جو طبقاتی جدوجہد کی بات کرتے تھے ۔ جواب ملا کہ اب یہ این جی اوز میں ہیں اور اپنا طبقاتی درجہ بلند کرنے میں مصروف ہیں۔ لہذا اگر خود پنجاب میں ایسی کوئی تحریک نہیں تو پھر بلوچستان اور سندھ کیا کریں ؟ یقیناپنجاب سے نفرت بڑھتی چلی جائے گی جو آگے چل کر ملک کے لیے تباہ کن ہوگی۔
لوگوں کے لہجہ میں تلخی تھی، غصہ اب تک نہیں تھا، ان میں محرومی کا احساس جھلکتا تھا۔تربت کی ساری معیشت کا دارومدار ایرا ن پر ہے۔ اناج ، سبزی، پھل، پٹرول اور تقریباً ہر چیز ہی ایران سے آتی ہے۔ شہر میں جگہ جگہ پٹرول اور ڈیزل کے ڈرم رکھے ہیں۔ پڑول ۱۳ روپے لٹر ہے۔ دوستوں نے کہا کہ پاکستان سے صرف حکمران آتے ہیں۔ خفیہ ایجنسیوں کے لوگ آتے ہیں تاکہ لوگوں کی نقل و حرکت پر نظریں رکھی جا ئے۔ کہنے لگے کہ ’’ہم میں سے ہر ایک ملک دشمن اور باغی نظر آتا ہے‘‘۔ میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں ان کی گفتگو سے سیکھتا رہا کہ لوگوں کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ محرومیاں اور مایوسیاں کس شدت سے اپنا اظہار کرتی ہیں؟ اگر ملک لوگوں کو نظر انداز کر دے تو لوگوں کا اس سے کیا تعلق رہ جاتا ہے؟
تربت کی آبادی چھ یا ساڑھے چھ لاکھ کی ہے۔اکثر مقانات کچی مٹی کے ہیں۔ پورے شہر میں کوئی خاص عمارت نظر نہیں آتی۔ سڑکیں برائے نام ہیں۔شہر کی معیشت کا دارو مدار ان لوگوں کی آمدنی پر ہے کہ جو خلیج میں ملازمت کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ پیداوار میں کھجوریں خا ص ہیں۔ تربت کو دوسرے شہروں سے ملانے کے لیے کوئی سڑکیں نہیں ہیں ۔ لہذا شہر مٹی و گرد میں اٹا ہوا خاموش اور اداس شہر ہے۔
چار بجے میرا لیکچر تھا جس کا عنوان ’’جاگیرداری، سرداری نظام اور مذہبی انتہاپسندی‘‘ تھا۔ کوئی دو سو کے قریب لوگ جمع تھے۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ بلوچستان کے کلچر میں ابھی بھی رواداری ہے۔ اس لیکچر میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ تھے۔ لوگوں نے بڑے تحمل اور خاموشی سے تقریر سنی۔ آخر میں خوب سوالات کیے۔ مگر بحث نہیں کی۔ چائے کے وقت بڑی تعداد ملنے آئی۔ ان میں سے اکثر نے میری کتابیں پڑھیں تھیں۔ سوالات ہوتے رہے، لوگ اپنے خدشات بیان کرتے رہے اور مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے۔یہ نوجوان اس ملک اور اس معاشرے میں اپنے مستقبل کی تلاش میں تھے۔ کیا سہانا اور آرام دہ مستقبل انھیں ملے گا یا نہیں؟ اور کیا یہ خاموشی سے اس استحصال اور محرومی کو برداشت کرتے رہیں گے؟ اگر کرتے رہے تو کب تک؟
دوسرے دن تربت سے گوادر جانا تھا۔ جب شہر سے نکلے تو معلوم ہوا کہ ان دونوں شہروں کے درمیان کوئی سڑک نہیں ہے۔ کچا راستہ ہے۔ بعض جگہ تو یہ کچا راستہ بھی نہیں تھا۔ گاڑی جھاڑیوں میں ہوتی ہوئی گزر رہی تھی۔میں سوچ رہا تھا کہ ایک طرف موٹر وے ہے تو دوسری طرف یہ کچی سڑکیں اور راستے۔ موٹر وے والے محب وطن ہیں اور ان کچی سڑکوں پر سفر کرنے والے مشتبہ لوگ ہیں۔ راستہ مین میدان بھی تھے اور پہاڑ بھی۔ کبھی کبھی یہ راستہ کچی مٹی کی چٹانوں کے درمیان سے گذرتا تھا۔ یہ مٹی کی چٹانیں، بارش اور ہواؤں کی وجہ سے تراشے ہوئے مجسمے معلوم ہوتی تھیں۔ اگر راستہ میں گاڑی خراب ہو جائے تو اس کی مرمت کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے۔ راستہ ویران اور سنسان ہے۔ کہیں ایک آدھ جگہ دور جھونپڑی ضرور نظر آئی۔ ورنہ نہ آدم نہ آدم زاد۔ درخت نہ سبزہ، ویران اور بے آب و گیاہ دشت ہے۔
تربت سے گوادر پہنچنے میں ساڑھے چار گھنٹے لگے۔ لیکچر کا وقت گیارہ بجے تھا۔ مگر ہم ایک گھنٹہ تاخیر سے پہنچے۔لوگ ہال میں منتظر بیٹھے تھے۔ گوادر کی آبادی ساٹھ ، ستر ہزار کی ہے۔ حاضرین ساٹھ یا ستر کے قریب تھے۔ لیکچر کا موضوع وہی تھا جو تربت میں دے آیا تھا۔ مگر سوالات مختلف تھے۔ خاص طور سے مجھے ایک سوال اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک نوجوان نے کہا کہ ’’آپ ہمارے سرداری نظام کو برا کہتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سردار ہی برے وقت میں ہمارے کام آتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں اور ہمارا تحفظ کرتے ہیں‘‘۔میں نے کہا کہ ’’آپ کی بات درست ہے ۔ مگر اس تحفظ اور مدد کے عوض آپ ایک بڑی قیمت ادا کرتے ہیں یعنی اپنی آزادی ، عزت و قار۔ آپ کا اور سردار کا رشتہ آقا اور غلام کا ہوتا ہے۔ وہ آپ سے وفا داری کی توقع رکھتا ہے۔ اس کے بدلہ میں آپ کی مدد کرتا ہے اگر آپ کو یہ سودا منظور ہو تو بخوشی آپ سرداری نظام کو برقرار رکھیں‘‘۔
سوالات میں پنجاب کی بالا دستی پر لوگوں نے کھل کر بات کی ۔ کہنے لگے گوادر میں کوسٹ گارڈز، خفیہ ایجنسیوں کے لوگ، فوجی چوکیوں پر تعینات لوگ سب پنجابی ہیں۔ یہ لوگ بسوں سے مسافروں کو اتار کر ان کی تلاشی لیتے ہیں۔ ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ آخر ہم یہ سب کب تک برداشت کریں ؟میرے پاس ان سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ گوادر آتے ہوئے جب ہم چیک پوسٹ پر پہنچے تو وہاں ایک فوجی جوان نے پہلے معلومات کیں کہ ہم کون ہیں؟ گوادر کیوں جا رہے ہیں؟ اس کے بعد جانے کے لیے راستہ دیا۔
لیکچر کے بعد میں نے پوچھا کہ ہم تو سنتے آرہے ہیں کہ گوادر میں ترقی ہو رہی ہے۔ اس کی بندر گاہ کو وسیع کیا جارہا ہے؟ انھوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ تو ہم بھی سن رہے ہیں۔ مگر گوادر آپ کے سامنے ہے۔ دیکھ لیں کہاں ترقی ہورہی ہے؟اس کے بعد گاڑی بٹھا کر وہ لوگ پہاڑ کے اوپر لے گئے۔ کیا خوبصورت نظارہ تھا۔ صاف و شفاف سمندر کا پانی۔ یہاں ایک آبادی کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ جہاں پاکستان کے حکمران طبقوں کے پلاٹ ہیں۔ ابھی مکانات نہیں بنے مگر سڑکیں بن گئی ہیں۔ شاید لوگ اس انتظار میں ہوں کہ گوادر بڑی بندرگاہ بنے اور ان کے پلاٹ سونے کے داموں بکیں۔بلوچستان میں مکران کا یہ علاقہ معاشی طور پر تو پس ماندہ ہے۔ مگر ذہنی اور سیاسی طور پر نہیں۔ نوجوانوں میں پختہ سیاسی شعور ہے۔ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں اور بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ معاشی پس ماندگی نے انھیں ذہنی طور پر پس ماندہ نہیں بنایا۔
میرے لیے مکران کا یہ سفر، لوگوں سے بات چیت ایک نئی دریافت ثابت ہوئی اور خود بھی سوچتا رہا اور دوستوں سے سوال بھی کرتا رہا کہ پاکستان کے حکمران طبقوں نے مشرقی پاکستان کے المیہ سے کچھ نہیں سیکھا۔ پنجاب کے حکمرانوں نے غیر پنجابیوں سے عزت و قار کے ساتھ بات کرنا نہیں سیکھی۔ ان کے ذرائع کو استعمال کر کے انھیں پسماندہ کر دیا۔ اہل بلوچستان اس کا اظہار کئی مرتبہ کر چکے ہیں۔ ان کی مزاحمتوں کو قوت سے کچل تو دیا گیا ہے مگر ان کے اندر کے زخم ابھی تازہ ہیں۔ مجھے یہ قول یاد آرہا ہے کہ جو قومیں تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتی ہیں۔ وہ سزا کے طور پر تاریخ کو بار بار دہراتی ہیں۔ مگر اس سزا کی قیمت بھی غریب اور مجبور عوام کو دینی ہوتی ہے۔
مشرقی پاکستان کے بحران نے کس کو متاثر کیا؟ صرف اور صرف عام لوگوں کو کیونکہ حکمران طبقے پر تو اس بحران کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب حکمرانوں کو اپنی بد عنوانیوں کی قیمت چکانا ہوتی ہے تو یہ بڑی بھاری قیمت ہوتی ہے۔ جب آتش فشانوں سے لاوہ ابلتا ہے تو وہ ہر شے کو تہس نہس کر کے جلا دیتا ہے۔ شاید ہمارے حکمران طبقے اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔
♦
پہلی دفعہ یہ مضمون ماہنامہ نیا زمانہ ، اپریل 2001 میں شائع ہوا۔






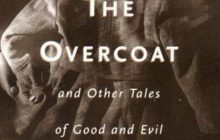





















One Comment