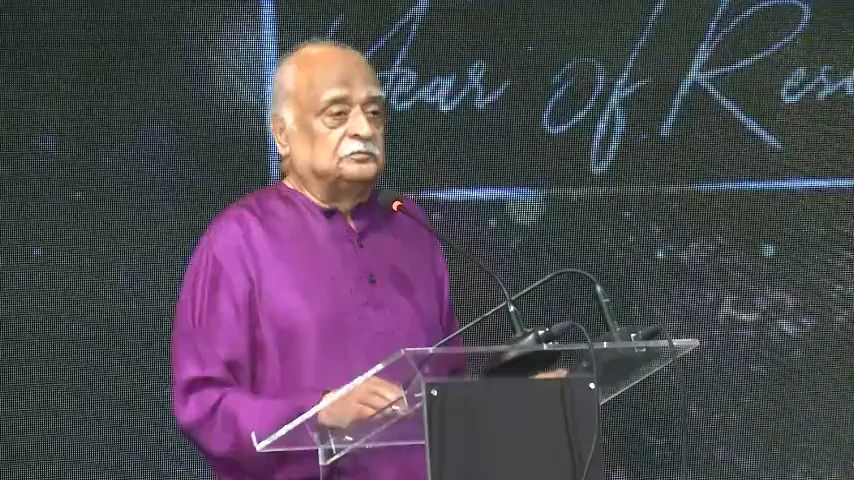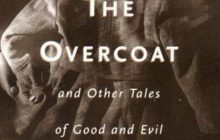ہم بڑے ہو رہے تھے اور ہمارا گاؤں دیہہ سے قصبے میں بدلتا جارہا تھا۔پہلے گاؤں سے شہر تک تانگہ جاتا تھا، پھر بس جانے لگی اور اب بسیں۔بسیں مقامی لوگوں کی ملکیت تھیں مگر ڈرائیور وغیرہ دوسرے دیہات اور قصبوں سے آئے ہوئے تھے جن کی تعداد کوئی دس پندرہ کے قریب تھی۔ان کے کھانے پینے کے لیے برگد کے درخت کے نیچے، برلب سڑک ایک ڈھابہ کھل گیا تھا جہاں صبح کو چنے پائے اور دوپہر کے وقت سالن روٹی دستیاب تھی۔
ڈھابہ تو بہت بعد میں بنا مگر ڈبہ گاؤں میں بجلی آتے ہی چند لوگوں نے خرید لیا تھا۔
’ڈبہ‘ جسے عام طور پر ٹی وی کہا جاتا ہے ہم بچوں کے لیے وہ درز تھی جس کے ذریعے ہم دیہاتی بچوں کی پہلی نسل اس تہذیب کا دیدار کرسکتی تھی جس کا دھندلا سا، نامکمل عکس کچھ کتابوں اور بہت سی کہانیوں نے ہمارے ذہنوں پر نقش کیا تھا۔ ہم خوش تھے کہ ڈبے سے ہی سہی ہم بد تہذیبوں نے بھی تہذیب میں نقب لگالی اور اب ادھر کے مکیں بھی اُدھر کے جلوے دیکھ سکتے ہیں۔
ان دنوں حسینہ معین، انور مقصود، فاطمہ ثریا بجیا اور ناہید سلطانہ اختر کے ذریعے ہم پہلی بار تہذیب یافتہ لوگوں کی زُبان، ثقافت اور رہن سہن سے واقف ہو رہے تھے۔ہم پر انکشاف ہو رہا تھا کہ ہمارے بڑوں جیسا لباس اور زُبان بولنے والوں کو تو تہذیب یافتہ گھرانوں میں ملازم رکھا جاتا ہے۔
یہ سب مہذب لکھاری ہمارے لیے اُن خاندانوں کی کہانیاں لکھ رہے تھے جن کے لیے ہمارے بڑوں جیسے بزرگ گاؤں سے دیسی گھی یا مرغیاں لے کر جائیں تو ان کے بچے مذاق اڑاتے تھے۔ہمیں سمجھ آرہی تھی کہ ایسی حرکات سے باز رہنے میں ہی بھلا ہے کیونکہ مرکزی دھارے میں ڈبکیاں لگانے والوں کے نزدیک ہم پینڈو اور گنوار تھے۔
ڈبے کو تو خیر ہم رات کے وقت ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے مگر دن کی روشنی میں ڈھابہ ہی ہم گنواروں کا سہارا تھا اور وہ ڈھابہ ہی تھا جہاں ہم نے ڈبے سے نکلی تہذیب کو پہلی بار سانس لیتے اور چلتے پھرتے دیکھا۔
ہوا یوں کہ ایک روز ہم بھائیوں نے فیصلہ کیا ہم دوپہر کا کھانا ڈھابے سے کھائیں گے کیونکہ یہ کھانا اُس گھی سے بنتا ہے جس سے بُو نہیں آتی اور جس کی مشہوری (کمرشل) ٹی وی پر چلتی ہے۔چونکہ بھائی بڑے اور میں چھوٹا تھا اس لیے روزانہ بھائی سالن کا انتخاب کرتے اور میں ڈھابے سے لے آتا۔کبھی دال، کبھی سبزی اور کبھی گوشت۔ مجھے یاد ہے اُس روز اُنہوں نے گوشت کی پلیٹ لانے کو کہا لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
ڈھابے پر پہنچا، سرسری دیکھا تو یقین نہ آیا۔ کئی بار دیکھا، آنکھیں مسل مسل کر دیکھا تو کہیں جا کر یقین آیا کہ میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہا۔
تہذیب ڈبے سے نکل کر ہمارے گاؤں کے ڈھابے پر لکڑی کی کُرسی پر بیٹھی دال سے روٹی کھا رہا تھی۔اس کا حلیہ، شکل اور لباس بالکل ان کرداروں جیسا تھا جن کی مدد سے ہمیں تہذیب سکھائی جا رہی تھی، کلین شیو، اُردو سپیکنگ، سوٹ، بُوٹ اور ٹائی میں ملبوس ۔۔۔ ہر نوالے کے بعد تنی ہوئی گردن آسمان کی طرف اٹھالینے والا بابو۔اس کی نرالی شان دیکھ کر میرے ذہن میں ایک خیال آیا جس پر عمل کرکے ہم بھی ایک جست میں مہذب ہوسکتے تھے۔’اگر مجھے دکھائی دینے والا یہ پہلا مہذب انسان دال کھارہا ہے تو ہم گوشت کیوں کھائیں؟‘۔
یوں میں گوشت کی بجائے دال لے آیا۔
بھائی دال دیکھ کر خفا ہوئے مگر وجہ جانتے ہی چھلانگ لگا کر ڈھابے کی طرف دوڑے۔بابو کھانا کھا چکا تھا اور اب سڑک کنارے سائیکل سواروں کا چالان کرنے میں مصروف تھا۔وہ منہ میں سگریٹ دبائے بڑے رعب سے اُردو میں سائیکل سوار کو آواز دیتا تو سائیکل کو جیسے خود بریک لگ جاتی۔پھر بڑی شان سے سوار کے پاس پہنچتا، کاغذات طلب کرتا، دیہاتیوں کے رنگ اڑجاتے، ہاتھ کانپتے اور وہ آٹھ آنے کا سکہ یا پھر ایک روپے کا نوٹ وصول کرکے سائیکل سوار کو ڈانٹ پلاتا تو وہ ایسے اُڑتا جیسے صیاد کے ہاتھ سے بچ نکلنے والا کوئی پرندہ۔
ہم دونوں بھائی شیشم کے درخت کے نیچے دُور کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے اور خوف سے بار بار غور کرتے رہے کہ کہیں ہم سائیکل پر تو سوار نہیں۔بابو تو دال کھا کے اور چند لوگوں کا چالان کرکے پھر کبھی نہیں آیا لیکن ہم کئی ہفتوں تک دال کھاتے رہے اور اس کی طرح اُردو بول کر دیہاتیوں پر رُعب جماتے رہے۔
ہم دال کھا کھا کر تنگ آگئے تھے اور میں روزانہ اس امید کے ساتھ جاتا کہ شاید آج بھی وہ ڈھابے پر موجود ہو اور دال کے علاوہ کچھ اور کھا رہا ہو لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔اس نے نہ تو دوبارہ آنے کا وعدہ کیا تھا اور نہ ہی کوئی تاریخ بتائی تھی۔ بھائی کو میرے انتظار کا علم ہوا تو انہوں نے مجھے باز رکھنے کے لیے کچی ٹاکی پر چوری چھپے ایک ساتھ دیکھی گئی کئی فلموں کے مستند اور متفقہ علیہ حوالے دیے جن میں گاؤں کی مٹیار کسی بابو کےعشق میں گرفتار ہوکر اس کی دُونی ترقیوں کی دُعا کرتے کرتے مرجاتی ہے لیکن بابو کبھی واپس نہیں آتا۔
بھائی کی مدلل باتیں سن کر مجھے صبر نہ آیا اور ایک روز میں نے ڈھابے کے مالک صدری سے اس کا پوچھ ہی لیا۔ پہلے تو وہ ہنس ہنس کر دُہرا ہوگیا, پھر اس نے بتایا کہ بابو تو بہروپیا ہے جو ہر روز بھیس بدل کر سادہ لوح دیہاتیوں کو لوٹتا ہے۔اپنی زبان، لباس اور حلیے سے لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے۔
یہ سن کر ہمیں دکھ ہوا مگر بہروپیا نہ سہی ڈبہ تو موجود تھا۔ یوں ہم ایک بار پھر ٹی وی ڈراموں سے تہذیب سیکھنے لگے۔
آنگن ٹیڑھا کے پنجابی لب و لہجے والے بھائی جان چودھری اور اس کی بہن پر خوب ہنستے۔آسمانی کرداروں میں کوئی زمین کردار دیسی گھی لاتا، تہذیب یافتہ بچے اس سے آنے والی بُو کی شکایت کرتے تو ہمیں بھی دیسی گھی اور مکھن سے بو آنے لگتی۔ڈبے سے تہذیب سیکھتے سیکھتے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ’مہذب لوگوں‘ کا اس دھرتی، اس کے رہن سہن، زبان اور رسم و رواج سے کوئی تعلق نہیں۔
اس دوران ڈھابے پر بڑے بڑے قصہ گو، لوک فنکار، شاعر اور فنکار جمع ہوتے رہے لیکن ہم ان سے بے خبر رہے۔وقت گزرتا گیا، دیہہ قصبہ اور قصبہ شہر بن گیا، ہم بڑے ہوگئے۔
ان قصہ گو، لوک فنکاروں اور شاعروں کے کام پر نگاہ ڈالی تو تہذیبی شعور جاگا اور خبر ہوئی کہ تہذیب کا تعلق ٹھونسے گئے نظریات سے نہیں ہر خطے کے مقامی لوگوں کے رنگ، ڈھنگ اور آہنگ سے ہے۔
ابھی کچھ روز قبل ڈبوں میں بیٹھ کر تہذیب سکھانے والوں کے چہروں سے نقاب اترے تو گیان ہوا کہ جیسے کھڑکی کے چوکھٹے سے دکھائی دینے والا آسمان آسمان نہیں ہوتا، اسی طرح ڈبوں سے نکلنے والی تہذیب تہذیب نہیں ہوتی۔
جو فرق ماں اور ڈبے کے دودھ میں ہے، وہی فرق مقامی اور ڈبے سے نکلنے والی تہذیب میں ہے۔ ڈبے سے نکلنے والی تہذیب ڈبہ بناتی ہے اورڈبے کے باہر جیون کی طرح فراخ حقیقی تہذیب مہذب۔
copied from social media
♠