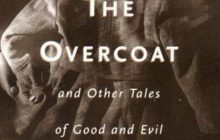مہر جان
جس طرح سیاسی بوٹس جو زندہ باد و مردہ باد تک محدود ہوتے ہیں اسی طرح سیاسی شعور سے بے بہرہ لکھاری بھی اکثر نمود نمائش میں مستغرق ہوکر اور ہر کسی کو خوش رکھنے کے چکر میں اپنا قومی فریضہ بھول جاتے ہیں،ان لکھاریوں کی کتابی باتوں میں اور اک عام باتونی کے باطن میں فرق نہیں رہتا۔ وہی بات دانشور رکھ رکھاؤ (یہاں رکھ رکھاؤ سے میری مراد تکلف ایکٹنگ کے سوا کچھ نہیں ہے) سے کررہا ہوتا ہے بالکل وہی بات بغیر رکھ رکھاؤ کے کوئی بھی باتونی کررہا ہوتا ہے۔
اخبار کی صحافتی لکھت اشتہارات کی نظر ہوجاتی ہے ، کتابیں لکھنے کی بھر مار ہوتی ہے، جیسا کہ کوئی کتاب لکھنے کا مقابلہ جاری ہو ، لیکن کتابوں میں کوئی نیا پن نہیں ہوتا ،بس چار چار صفحوں کے حوالہ جات ضرور ہوتے ہیں تاکہ کتابیں ضخیم دکھائی دیں،اور اک ہی کتاب کو چار چار حصوں میں تقسیم کرکے چار چار کتابیں مارکیٹ میں لائی جاتی ہے تاکہ مصنف کی مارکیٹنگ ہوسکے۔رسل و رسائل کے صرف یہاں وہاں سے پیٹ بھرے جاتے ہیں ، اس دوران دانشوری کا ایسا چسکہ بھی جنم لیتا ہے کہ ایک ایک پیرا میں چار چار مصنفین کے ناموں کے تذکروں سے دانش کا سینہ چوڑا کیا جاتا ہے ، جس سے لکھاری کا اصل مقصد و مفہوم کھو جاتا ہے ۔
اب دانشور کی جگہ جس نے معاشرے کی خس و خاشاک کی چنگاریوں سے حاکم سامراج کے لیے آگ لگانی تھی انکی جگہ معاشرے میں عام سطحی بابے پیدا ہوتے ہیں جو کہ پنجاب میں شہاب الدین شہاب ، واصف علی واصف ، اشفاق احمد کی صورت جنم لیتے رہتے ہیں ، جن سے تعلق فقط عقیدت کا بن جاتا ہے یہاں اتنا کھوکھلا پن ہے کہ محکوم قوم کے بیشتر لکھاری ہمیشہ سے حاکم کے ریاستی لکھاریوں کی لٹریری اجارہ داری کا شکار ہوتے ہیں ، وہ اُن کے سحر سے نکل نہیں پاتے ، ان کی طرز زندگی ، طرز گفتگو ، طرز تحریر سے اس قدر اثر لیتے ہیں کہ وہ خود آرزو ئیں پالتے ہیں کہ کاش میری طرز زندگی ، طرز گفتگو یا طرز تحریر ایسی ہوتی ، وہ ان کے ساتھ چند منٹ کی گفتگو یا چند توصیفی کلمات کو اپنا سرمایہ حیات سمجھتے ہیں۔
ابھی کچھ عرصہ نہیں گذرا کہ یہاں کے قلمکار ریاست کے عام نمائندہ لبرل نظریات رکھنے والے لکھاریوں کے لفظی جگالی یا واقعہ نگاری سے متاثر تھے ، لیکن شکر ہے بلوچستان پہ مکالمہ کی وجہ سے ریاست کے نمائندہ لکھاری اپنے آپ کو ایکسپوز کرگئے کہ وہ فقط سبز ھلالی رنگ میں رنگے ہو ئے ہیں ، اور اس ھلالی رنگ کے لیے ان کے پاس اخلاقی و سیاسی و تاریخی کوئی جواز نہیں ،۔ہاں البتہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ریاست کے پولیٹکل سوسائٹی کی بجائےریاست کے سول سوسائٹی کی ذریعے اس سبز ھلالی پرچم کے لیے بلوچ قوم کی رضامندی حاصل کی جائے ۔
لیکن تا حال بلوچ قوم کی مزاحمتی سیاست کی بدولت (پولیٹیکل سوسا ئٹی) سبز ھلالی پرچم بلوچ قوم کے لئے نامانوس ہوتا جارہا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ حاکم کا نمائندہ لکھاری فلسفیانہ بحر و بر سے واقف ہے یا وہ علم و دانش کے خزانہ سے مالامال ہے ، (کا ش ایسا ہوتا ) اور محکوم کے قلمکار اسی وصف کی بنیاد پہ ان کے قصیدے پڑھتے ، یا ان کی جرات کی بناء پہ ان کو سراہتے لیکن بدقسمتی محکوم لکھاریوں کی ہے کہ وہ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں ، وہ اپنے آپ کو جب دوسروں میں تلاش کرتے ہیں ، پھر انکے اقوال سے لے کر لکھت تک مصنوعی پن کا شکار ہوجاتی ہے ، وہ زندگی بھر توصیفی کلمات کے محتاج ہوتے ہیں وہ پاپولر ازم (سطحی شہرت) جیسی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں ۔وہ اپنے سماج سے جڑے رہنے کی بجائے دوسرے کے سماج کے تضادات کو اپنے سماج پہ لاگو کرکے اُسی سماج کے لکھاری کا ہم پلہ بننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔
کاش محکوم قوم کے لکھاری حضرات اپنے اندر اس کھوکھلے پن کو فلسفہ و ادب سے شاداب و سیراب کرتے ، آج کل کے ٹرینڈز سے نکل کر فلسفہ و اکیڈیمیاء کی جانب آتے اور حاکم طبقہ کی نمائندہ لکھاریوں کے سامنے سیسہ پلائ ہوئ دیوار بن کر اپنی قوم کے لوگوں کو اس سے آگاہی دیتے کہ کیسے ان کے لفظوں کی جگالی ، ان پہ لگے ہوئے مختلف ترقی پسندی و لبرل ازم کے برانڈز کے اندر ریاستی دہشت گردی پنہاں ہے۔
دوسری طرف ریاست کے نمائندہ لکھاریوں کے تمام تر دعوں کے باوجود اکیڈیمیاء میں عمرانیات و جدلیات کے سکالرز اپنے کہے کا تضاد پیش کرتے ہیں وہ دراصل روایت کے غلام ہوتے ہیں۔حالانکہ علمی دنیا میں وہ سب اسی خوش فہمی کا شکار ہیں یعنی یہی یقین کرتے نظر آتے ہیں (شائد یہ کوئی واضح دعوی نہ ہو) کہ ہمارے تجزیات ہر قسم کی قدامت، عامیانہ پن اور زندگی کی ہر پل بدلتی ہوئی پسماندہ سوچ سے مبرا ہیں۔ مگر وہ لوگ اپنی دنیا کی ھم عصر دانشورانہ روشوں ، فکری، وقتی ریتوں سے ابھی تک مانوس بھی نہیں ہیں کہ فلسفہ و ادب سے بلد دانشور کسی ریاستی حصار میں قید نہیں ہوتا ، وہ مذہبی اقلیت و قومی محکومیت کے حق میں اپنے قلم کی سیاہی کو لہو میں بدلنے کا ہنر رکھتا ہے لیکن ایسا روزگار و ہنر یہاں میسر نہیں ہے اور ستم ظریفی یہ ہے محکوم قوم کے لکھاری ان نام نہاد اسکالرز سے آگے کا سوچ بھی نہیں سکتے ۔
گرچہ فینن نے محکوم کے لکھاریوں کی ڈی کالونائزیشن کے تین مراحل بتائے ہیں لیکن یہاں پہلا مرحلہ ہی سر ہونے کو نہیں آرہا ، جس طرح مزاحمت کار کی بندوق کالونائزر کی بندوق کا مقابلہ کررہی ہے اسی طرح محکوم کا قلم بھی کالوناہزر کے قلم کا مقابلہ کرے تب جا کر بات بنے گی۔ اب محکوم کا لکھاری اس مقابلہ میں کہاں کھڑا ہے میرے خیال میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ۔ خیالی و دیومالائی دنیا میں ہر گھوڑ سوار اسی زعم میں مبتلا ضرور ہے کہ وہ اس قوم کا ترقی پسند دانشور ، یا سارتر و فینن و ایڈورڈ ہے لیکن اس زعم کا کیا کیا جاسکتا ہے؟ ہاں البتہ یہ طے ہے کہ اس محکوم قوم نے ان لکھاریوں کو انکی مزدوری سے زیادہ اجرت دی ہے۔
اس ساری صورتحال میں محکوم کے لیے فلسفہ پڑھنا کیوں ضروری ہے ؟ کیا فلسفہ ایک واحد ہتھیار(فکری) بچ جاتا جہاں محکوم خود تنقیدی سے خود شعوری کی جانب اپنا سفر جاری رکھے ، عقیدت سے زیادہ تعقل اور ایک مکمل فکری و سیاسی پروگرام کے تحت مزاحمت کا دم بھرتا رہے ،خاص کر اس وقت جب محکوم مزاحمت میں پیش قدمی کررہا ہو ، ان بنیادی سوالات کا جواب دینے سے پہلے فلسفہ کے مسخ شدہ تصور کی وجوہات ، تعارف فلسفہ ، فلسفہ کا معاشرہ سے تعلق ، اور آخر میں محکوم کو فلسفہ پڑھنے کی ضرورت پہ سیرحاصل مباحث درکار ہے ۔تاکہ محکومیت کی زنجیر فلسفہ کی حرارت سے پگھل سکے ۔
(جاری ہے)