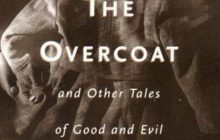میری خواہش ہے بلوچ نوجوان مارکس کو خود پڑھ کر اپنی تنقید سامنے لائیں۔بابا مری
مہر جان
فلسفہ کا نام سنتے ہی لوگ اسے انتہائی مشکل ،ناقابل فہم ، خشک اور ایک ایسا علم سمجھتے ہیں جس کا عوام کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ، یعنی اشرافیہ کے لیے اک مختص “ذہنی عیاشی کا علم” جس کا عام معاشرے سے کوئی تعلق داری نہیں بنتی ، ایک ایسا علم جو صرف زمین سے نیچے اور آسمان سے اوپر کی باتیں کرتا ہے ، یہ بارہا کہا جاتا ہے کہ فلسفہ لاینحل مسئاہل کا انبار ہے ،فلسفہ کے پاس جواب نہیں ، دو ہزار برس سے فلسفہ کے وہی سوالات و مسائل ہیں جن سے فلسفہ آج بھی نبرد آزماء ہے۔
بڑے بڑے پروفیسرز فلسفہ کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں “ فلسفہ ہمیں ایک ایسی منزل کی جانب چلتے رہنے کا مشورہ دیتا ہے کہ جس راہ کا نہ تو کوئ آغاز ہے اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے” یعنی “ یہ تو کسی تاریک کوٹھری میں اس کالی بلی کی تلاش بسیار کا ایک ایسا تھکا دینے والا مسلسل عمل ہے کہ جو وہاں موجود ہی ہوا نہیں کرتی” فلسفہ پڑھنے والے کو عموماً معاشرہ سے بیگانہ گر دانا جاتا ہے ،اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ فلسفہ پڑھنے والے مذہب و سماج بیزار سے ہوتے ہیں اور اک خیالی دنیا کا باسی ہوتا ہے۔ اس روش کو عام کیا گیا ہے کہ فلسفہ عمل سے دور کرتا ہے ، یعنی فلسفہ پڑھنے والا عملی طور پہ ناکارہ ہوتا ہے ، وہ صرف سوچتا رہتا ہے یا خیالی دنیا میں رہ کر صرف ،سوالات اُٹھاتا ہے جبکہ عمل کے لیے حد سے زیادہ سوچنا اور سوال پہ سوال کرنا مضر ہے ۔
دراصل فلسفہ اپنی نیچر میں ایک خطرناک ترین علم ہے ، اس لیے اسے انتہائ مشکل ، ناقابل فہم ، خشک کہہ کر اس سے ہمیشہ اجتناب کیا گیا ہے ۔ اور فلسفہ تصور کو عموم کے لیے مسخ کیا گیا ہے ۔ فلسفہ کو سوال در سوال سے جوڑ کر رد فلسفہ و منطق پر بھی بہت کچھ لکھا جا چکا ہے ، سائنس کو فلسفہ پہ برتر کرکے فلسفہ کو قصہ پارینہ بنانے کی تگ و دو بھی کئی عرصے سے جاری و ساری ہے ، جس کو سائینٹسزم کہا جاتا ہے ،جو ایسے لوگوں کا مشغلہ ہے جن کو نہ فلسفہ کا پتہ ہے نہ وہ سائنس کی شدھ بدھ رکھتے ہیں ، گر دیکھا جائے ، سائنس سے بڑھ کر سچ “سائنس کی سچائی” ہوتی ہے جو کہ “سائنس” کا نہیں بلکہ” فلسفہ سائنس” کا ڈومین ہے ، اور یہ اصول سائنس سے لے کر سوشل سائنسز تک محیط ہے ۔
مثلاً تاریخ سے بڑھ کر سچ ، “تاریخ کی سچائی” ہوتی ہے جو فلسفہ تاریخ کا ڈومین ہے ، اس موضوع پہ بہت کچھ اکیڈ یمیاء میں لکھا جارہا ہے کہ کیا سائنسی دائرہ کار میں سچائی “منتقل “ ہوتی ہے یا پھر سچائی “ قائم” ہوتی ہے ، کارل پوپر اس حوالے سے فلاسفی آف سائنس میں بہت کام کرچکا ہے ۔ اسی طرح تاریخ کے حوالے سے مباحث چل رہی ہے کہ تاریخ نگاری میں تاریخ سے بڑھ کر تاریخ نگار کی تجربیت کس قدر شامل حال ہے ؟ ھیگل کا فلسفہ تاریخ تو جرمن ریاست کی تشکیل کے لیے معاون کار ثابت بھی ہوا، سائنس ، تاریخ اور فلسفہ کو گر یکجاء کیا جائے تو” فلسفہ سائنس تاریخ کے بغیر خالی ہے ، تاریخ سائنس فلاسفی کے بغیر اندھا ہے”۔ اسی تناظر میں فلاسفرز میٹا فزکس کو بھی ساہنس کا ملکہ کہتے ہیں ، حتی کہ لیوی اسٹراس اپنے لیکچر “دیو مالائی فکر اور سائنس کا سنگم” میں اس احساس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ”سائنسی فکر کی بنیاد دیو مالائی فکر ساختیاتی نوعیت ہی میں پوشیدہ ہے”۔سائینٹیسزم پہ یقین رکھنے والے اپنے تہیں یہ گماں لگا کر بیٹھے ہیں کہ یہ دور سائنس کا دور ہے جہاں فلسفہ قصہ پارینہ بن چکا ہے ۔
الغرض فلسفہ کے خطرناک نیچر کی وجہ سے فلسفہ تصور کو معاشرہ میں اس قدر مسخ کیا گیا ہے ، کہ اکثر طلباء فلسفہ کو اکیڈمک سمجھ کر بھی اجتناب فرماتے رہتے ہیں لائبریریوں میں فلسفہ کے سیکشنز پہ دھول جمی ہوئی نظر آتی ہے ، اگرچہ آج کل لائبریریوں میں ادب اور تاریخ کی طرف بھی دیمک چل پڑی ہے، لائبریریاں اپنا اصل مقصد کھوچکی ہیں ،جہاں صرف بابو بننے کی مشق جاری رہتی ہے ،الماریوں میں پڑی کتابوں کوسوائے جنرل نالج کے کوئی چُھوتا بھی نہیں، کہ جس سے فلسفہ و ادب و تاریخ کی آبیاری ہوسکے، سونے پہ سہاگہ یہ ہوا کہ پبلشر ز بھی مواد کے بجائے ایک مشہور بیانیہ کے تحت عنوان ڈھونڈ کر کتابیں چھاپ کر پیسے کما رہے ہوتے ہیں۔
اکیڈمیز جن کا اصل کام فلسفہ و ادب کا فروغ تھا ،اپنی اصل میں قومی ادارے نہیں بلکہ ریاستی فنڈڈ ادارے ہیں جن کا فلسفہ و ادب کا دور دور تک واسطہ نہیں ،اکیڈمیز میں مافیاز پھل پھول رہے ہیں جن کا فلسفہ و ادب کبھی بھی درد سر نہیں رہا ، اور نہ ہی کبھی باعث سرور سکون رہا ہے، اس سب کا بلاخر یہی نتیجہ نکلنا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اس طرح کی صورت حال میں بانجھ پن کا شکار ہوجاتا ہے ، قحط الرجال کا دور دورہ ہوتا ہے ،ادبی صورتحال نقل در نقل میں مبتلا رہتا ہے، اور ادب کی چاشنی معدوم ہوئی چلی جاتی ہے ۔ دوسری طرف سیاسی و زرخیز و فلسفیانہ ذہن کی بجائے بوٹس سیاسی میدان میں اترتے ہیں ، جو زندہ باد و مردہ باد تک محدود ہوتے ہیں ،سیاسی تنقید کی جگہ فقط تعریف توصیف و خوشامدی کلچر جنم لیتا ہے، جو محکومیت کو توانا کرتا ہے۔
فلسفیانہ ادراک و سیاسی شعور جو کسی بھی ہتھیار سے کم نہیں ،اس طرح کے ہتھیار بند ذہن اپنے مزاج کی وجہ سے یا تو الگ تھلگ ہوجاتے ہیں، یا پھر مختلف حربوں سے انہیں بے دخل کیا جاتا ہے ، تاکہ سیاسی شعور کو فروغ نہ ملے، محکوم کا اصل ہتھیار بندوق سے بڑھ کر سیاسی شعور ہوتا ہے ، شعور اور بندوق کا تعلق بھی ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے ، دونوں ایک دوسرے کے لیے معاون کار ہیں لیکن کسی بھی محکوم کے لیے بنیاد ، فلسفیانہ ادراک و سیاسی شعور ہوتا ہے ۔
یہ سیاسی شعور ہی تھا ،کہ آغا عبدلکریم نے “مزاحمت کی سیاست” کی راہ اپنائی جو تاحال کسی نہ کسی حوالے سے جاری ہے ، سیاسی شعور نہ ہونے کے سبب سیاسی اذہان کو یرغمال بنایا جاتا ہے ، وہ شخصیت پرستی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے ، اور یہ زنجیریں ان کے لیے غیر مرئی ہوتی ہے، وہ زندہ باد و مردہ باد سے آگے کا سوچ بھی نہیں سکتا ، نہ اپنی سیاسی قیادت پہ سوال اٹھا سکتا ہے ، وہ قیادت کے سحر میں اس قدر مسحور ہوتا ہے ، کہ اپنے اردگرد کے حالات بھی اس سحر سے اُسے نہیں نکال سکتا اور آخر کار سیاسی طور پہ زنگ آلود ہوکر مصلحت پسندی کا شکار ہوجاتا ہے ۔ اور وہ ایک طرح سے یس مین بن جاتا ہے ۔
۔( جاری ہے )۔